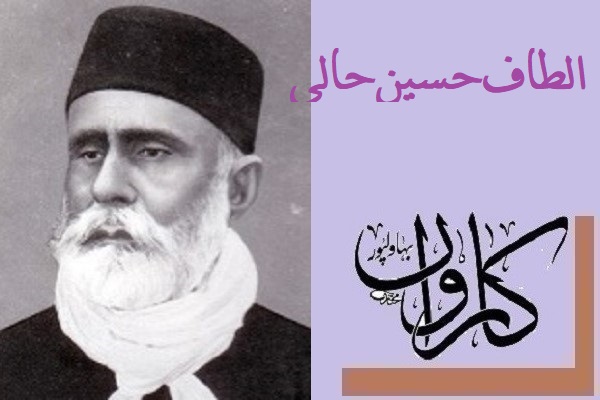کچھ کذب و افترا ہے کچھ کذبِ حق نما ہے
(حالی کی قومی شاعری کا مابعد نو آبادیاتی سیاق)
………………………………
اردو میں حالی کی قومی شاعری اور اس کے کردار پرخاصا لکھا گیا ہے۔ کچھ اچھے مقالات بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے اچھے ہونے کی وجہ محض’’ معلومات‘‘ کی فراہمی ہے۔ یعنی ان میں قومی شاعری کا مستند تذکرہ مل جاتا ہے۔ حالی کی قومی شاعری نے قومیت پرستی کے تصورات کے فروغ میں کیا کردار اداکیا اور یہ تصورات کیاان کے شعری تخیل کی پیداوار تھے یا کہیں سے مستعارتھے، یعنی کسی اندرونی تحریک کا نتیجہ تھے یا بیرونی دباؤ کے پیدا کردہ تھے ؟ان سوالوں سے عام طور پرتعرض نہیں کیا گیا۔ نیز آخر کیا وجہ ہے کہ قومی ادب کا تصور انیسویں صدی کے اواخر ہی میں سامنے آیا؟اس مقالے میں انھی اوران سے ملتے جلتے سوالوں کا جواب تلاش کرنا مقصود ہے۔
وجہ محض’’ معلومات‘‘ کی فراہمی ہے۔ یعنی ان میں قومی شاعری کا مستند تذکرہ مل جاتا ہے۔ حالی کی قومی شاعری نے قومیت پرستی کے تصورات کے فروغ میں کیا کردار اداکیا اور یہ تصورات کیاان کے شعری تخیل کی پیداوار تھے یا کہیں سے مستعارتھے، یعنی کسی اندرونی تحریک کا نتیجہ تھے یا بیرونی دباؤ کے پیدا کردہ تھے ؟ان سوالوں سے عام طور پرتعرض نہیں کیا گیا۔ نیز آخر کیا وجہ ہے کہ قومی ادب کا تصور انیسویں صدی کے اواخر ہی میں سامنے آیا؟اس مقالے میں انھی اوران سے ملتے جلتے سوالوں کا جواب تلاش کرنا مقصود ہے۔
٭
اردوادب کے قومی کردار کی باضابطہ بحث شیخ عبدالقادرنے اٹھائی۔ اگست ۱۸۹۳ء میں انھوں نے لاہور میں ’ینگ مینز محمڈن ایسوسی ایشن‘کے جلسے میں ’اردو لٹریچر‘ کے عنوان سے مضمون پڑھاجو اسی ماہ ’پنجاب میگزین‘میں شائع ہوا اور ۱۸۹۸ء میں منظرِ عام پر آنے والی ان کی انگریزی کتاب’دی نیو سکول آف اردو لٹریچر‘میں پہلے باب کے طور پر شامل ہوا۔ یہ مضمون بنیادی طور پر ان انگریزی خواں نوجوانوں کے لیے لکھا گیا جو عمومی طور پرورنیکلر ادب اور خصوصی طور پر اردو ادب کو قابلِ مطالعہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے لیے ادب سے مراد فقط انگریزی ادب تھا۔ ہندوستان میں جو کچھ انگریزی ادب کے علاوہ ادب ہونے کا مدعی تھا،وہ ان کے نزدیک ناقابلِ اعتنا تھا۔ عبدالقادر انگریزی میں مخاطب ہوکر اردو ادب کی اس معنویت کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو انگریزی لالٹینوں کی روشنی سے منور ذہنوں کے لیے قابل فہم ہو۔ واضح رہے کہ وہ انگریزی ادب کی اس افادیت اور اہمیت کو چیلنج نہیں کرتے،جو انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے یہاں عام طور پر موجود تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ انگریزی کی مخالفت کیے بغیر اردو کی حمایت پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام تھا۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ نو آبادیاتی برعظیم میں مشرق و مغرب کے ’فرق و مخالفت‘ کی لکیر بے حد واضح تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ سر عبدالقادر انگریزی ادب کی ’برتری،آفاقیت اور لازمی ضرورت‘کے تصور کو کوئی گزند نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان کے نزدیک اس مشکل کا حل اردوادب کا ایک ایسا تصور متعارف کروانے میں تھاجو انگریزی تصورِ ادب کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اس عہد میں انگریزی ’روشن خیال اور مہذب بنانے‘کی قوت سمجھی جاتی تھی۔ سر عبدالقادراسی سیاق میں قومی ادب کا تصور متعارف کرواتے ہیں:
’’میں[ورنیکلر/ اردو ادب کو]کیوں اہم سمجھتا ہوں،اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں تک رسائی،کسی بھی مقصد کے لیے ان کی ہمدردیاں طلب کرنے،ان کی محبت حاصل کرنے،ان کا اعتماد جیتنے، انھیں روشن خیال اور مہذب بنانے کا بہترین طریقہ،ورنیکلر کا میڈیم ہے۔ فقط یہی زبان ملک کو [وہ]قومی ادب فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے،جس کے بغیر کوئی قوم کوئی قابلِ ذکر ترقی نہیں کر سکتی؛اس لیے کہ قوم جو کچھ بھی ہے،اسے بنانے میں ادب غیر اہم کردار ادا نہیں کرتا۔‘‘۱
ان خیالات کا مطالعہ کرنل ایف جے گولڈسمڈ کے مضمون’’ مشرق میں قومی ادب کے تحفظ پر چند خیالات‘‘ کی روشنی میں کیجیے جوکرنل صاحب نے ۳۰ نومبر ۱۸۶۳ء کو رائل ایشیاٹک سوسائٹی، لندن میں پیش کیا تھا۔ گولڈ سمڈ کہتا ہے کہ:
’’ ہمیں لوگوں کی باطنی زندگی اور ان کے جی کی بات کا کچھ علم حاصل کرنا چاہیے،جیسا کہ ان کے اپنے ترجمان ظاہر کرتے ہیں؛سادہ لفظوں میں ان کے شاعر اور فلسفی۔ دس میں سے نو مثالوں میں ان کی زبان ہمیں پوری طرح قبول ہے کیوں کہ یہ اپنے ہم وطنوں کو انتہائی موثر انداز میں مخاطب کرتی ہے۔ یہ دل اور گھر سے نکلتی اور دل کو مخاطب کرتی ہے۲۔ ‘‘
گولڈسمڈ یہاں مقامی زبانوں ہی کا ذکر کرتا ہے اور اس ضمن میں اپنی اس ’قومی‘ نارسائی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اپنی رعایا کو سب کچھ دے سکتے ہیں،نہیں دے سکتے تو وہ ان کا قومی ادب ہے۔ اس کے یہ جملے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں:
’’ اگر قواعد کی کتاب درکار ہے،انگلستان کسی کو تیار کرنے کی ہدایت کردیتا ہے؛اگر حروف ِ تہجی کم ہیں تو کسی ہنر کار کی توجہ اس کمی کو دور کرنے کی طرف مبذول کرا دی جاتی ہے،اور اس کے حکم پر سکول کی نصابی کتب مقامی زبانوں میں پریس سے جاری ہوجاتی ہیں،مگر انگلستان [ان کا] قومی ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔‘‘۳
یہاں ایک بات واضح رہے کہ گولڈ سمڈ اقرار کرتا ہے کہ ہندوستان کی مقامی زبانوں میں قومی ادب موجود ہے، اور اسے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے اس مضمون میں سسی پنوں کی داستان پر چند باتیں لکھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ سسی پنوں اور دوسری لوک داستانوں کو قومی ادب کہتا ہے کہ یہ دل سے نکلتی اور دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ’’قومی ادب‘‘ یورپی حکم رانوں کے لیے ایک گنج گراں مایہ تھا: یہاں کی اجتماعی سائیکی میں جھانکنے کا؛اس تصورِ کائنات کو سمجھنے کا جو دنیا اور سماج کو دیکھنے اور برتنے کی بنیاد ہوتا ہے۔ یورپی حکمران قومی ادب کی تحسین سے زیادہ اس کی تفہیم چاہتے تھے۔ وجہ بے حد سادہ تھی:اجتماعی سائیکی کا علم، اس پر دسترس کو ممکن بنا تا تھا۔ تاہم گو لڈ سمڈ اور دوسرے یورپی منتظم و شرق شناس ’نئے قومی ادب‘ کا تصور بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ لوک داستانیں ہندوستان کی اس نئی اجتماعی سائیکی کی ترجمان نہیں تھیں جو یورپی اثرات کے نتیجے میں صورت پذیر ہورہی تھی۔ علاوہ ازیں وہ نئے قومی ا دب کے ذریعے نئی حسیت بھی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو سکول کی نصابی کتاب تیار کرنے سے مختلف تھا۔ چناں چہ کہیں تو اسی لکیر پر ہمارے شاعر چلے اور کہیں انھوں نے اسی ادب کو یورپی حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کا ذریعہ بنایا۔
بہ ظاہر سرعبدالقادر کے یہاں انگریزی کا ذکر نہیں ہے،مگر حقیقت یہ ہے کہ قومی ادب کے اس تصورکا سارا تاروپوداسی کی مدد سے تیار ہوا ہے۔ مثلاًانگریزی اشرافیہ کی زبان ہے اوراردو عام لوگوں کی زبان ہے۔ اردو کو ورنیکلر کہنا ہی انگریزی کے مقابلے میں ہے۔ ورنیکلرلاطینی لفظ vernaسے ماخوذ ہے،جس کا مطلب ’’خانہ زادغلام‘‘ ہے اور ورنیکلر کا لغوی مفہوم’’خانہ زاد غلام سے متعلق‘‘ ہے۴، لہٰذا ورنیکلر غلاموں کی زبان ہے۔ نیز’’ورنیکلر سے مراد وہ الفاظ ہیں،جو اس وقت تک ہمیں مانوس لگتے ہیں جہاں تک ہم زبان کے گھریلو حصے کویاد رکھ سکتے ہیں،بہ مقابلہ ان اصطلاحات کے جنھیں ہم نے اکتساب کیا ہے۔۔۔۔۔اکثراس کا اطلاق خاص طور پر دہقانی بولی پر کیا جاتا ہے‘‘۵ورنیکلر کے یہ مفاہیم برعظیم کی تمام زبانوں سے معاملہ کرتے ہوئے انگریزحکمرانوں کے پیش ِ نظر رہتے تھے۔ ’’غلاموں کی زبان‘‘ مقامی ہوتی ہے؛محدود، پس ماندہ اوردہقانی یعنی غیر شائستہ ہوتی ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر ’’غلاموں کی زبان‘‘ غلاموں ہی کی طرح غیر اہم ہوتی ہے،اور اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے، مگر یہ عمل خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ نوآبادکار بعض عملی انتظامی، عدالتی ضرورتوں کے تحت مقامی زبانوں کا علم حاصل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اسی دوران میں انھیں یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ زبان لوگوں کی روحوں کے اسرار جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جاننا فتح کرنا ہے۔ یہ اصول استعماریت کی بنیاد میں پتھر کا کام دیتا ہے۔ لیوس فرڈی نینڈ سمتھ نے با غ و بہار کے انگریزی ترجمے کے دیباچے میں لکھا ہے:
’’ان(ہندوستانیوں) کی زبان سے ناواقفیت ۔۔۔کسی وقت ہندوستان میں مقامی فوجیوںمیں ایک ایسا شعلہ بھڑکا سکتی ہے جسے ملک میں موجود تمام یورپیوں کے خون سے بھی نہیں بجھایا جاسکتا۔‘‘۶
لہٰذا ورنیکلر کو نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا جاتا۔ ورنیکلر کا علم ’’غلاموں‘‘تک رسائی کا ذریعہ ہوتا ہے؛رسائی کے تمام لغوی، مرادی اور استعاراتی مطالب کے ساتھ۔ ان کے ارادوں،ان کے تعصبات،ان کے عقائد،ان کی ذہنی اور ثقافتی دنیا تک رسائی کا ذریعہ! اس دنیا کو ہمیشہ ایک ’’شے‘‘ سمجھا جاتا ہے، جسے جاننے کے نتیجے میں تسخیر کیا جاسکتا؛جسے کسی نہ کسی مصرف میں لایا جا سکتااورجسے نئے سانچے میں ڈھالا جا سکتاہے۔
چوں کہ ورنیکلرکی محدودیت اورپس ماندگی کے تصورات ایک اشرافیہ زبان کے مقابلے میں اور اسے معیار تسلیم کرتے ہوئے قائم کیے جاتے ہیں،اس لیے اس اشرافیہ(یعنی انگریزی) زبان کے ذریعے ورنیکلر کو ’مہذب اور روشن خیال بنانے‘کا منصوبہ عین فطری، ضروری اور ورنیکلر کے حق میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی منصوبے کے نتیجے میں ورنیکلرمیں قومی ادب پیدا ہوتا ہے اورورنیکلرادب کی نئی تاریخوں میں اسی ادب کوقومی ادب قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ ورنیکلر میں قومی ادب کی تاریخ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے یورپی ادب کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ورنیکلر کے ادب کی تاریخ دو واضح حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے:ــــ’قومی ادب‘ اور’ قومی تصور کے بغیر ادب‘۔ دوسرے لفظوں میں نیا قومی ادب، پہلے سے موجود ادب کو نام دینے اور اس کا مرتبہ متعین کرنے کی ’پوزیشن‘اختیار کر لیتا ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں سر عبدالقادر کی یہ رائے ملاحظہ فرمائیے:
’’اگرہم اپنے وطن میں حقیقی اور سچی شاعری کی قدر رکھتے ؛اگر ہمارے مصنفین میں آفاقی احترام کے حامل چند نام ہوتے ؛اگرہمارے پاس کوئی قومی شاعرہوتا اور قومی شاعری ہوتی تو ہندؤ ں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا سب سے اہم مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔‘‘ ۷
گویا ’قومی تصور کے بغیر ادب‘حقیقی اور سچی شاعری سے محروم تھا۔ سر عبدالقادر نے یہ بات کھل کر نہیں کہی،مگر اسے مخفی بھی نہیں رکھ سکے کہ ہماری شاعری ’حقیقی اور سچی شاعری‘ نہیں تھی۔ اس عہد میں اردو شاعری مبالغہ آمیز، خیالی اور ان نیچرل ہونے کا الزام بھی سہہ رہی تھی اور انجمنِ پنجاب کے تحت اردو شاعری کی ’اصلاح‘ کی تحریک کا بنیادی مقصد بھی اسے ’خیالی اوران نیچرل‘ مضامین سے نجات دلانا تھا اور اسے ’حقیقی اور سچی شاعری‘سے مالامال کرنا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سر عبدالقادر اس الزام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ ’لبرل انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے روشن خیالوں‘ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ وہ اردو ادب پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں زلفِ مشکیں، خال سیاہ اور موے کمر کے سوا کچھ نہیں،لہٰذا اس کا مطالعہ وقت کا زیاں ہے۔ اس کے جواب میں سر عبدالقادر کہتے ہیں کہ ’’یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک قدامت پسند ملاّ انگریزی کے ابتدائی قاعدے کے سننے سے حاصل ہونے والے تاثر کی بنیاد پریہ کہے کہ انگریزی میں بلی اور کتے اور خنزیر کے سوا کچھ نہیں‘‘۔۸ یہ جواب خیال انگیز اور مسکت ہونے کے باوجود دراصل ’لبرل انگریزی خوانوں‘کواردو ادب کے مطالعے کی ترغیب دینے کی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔ سر عبدالقادر اردو شاعری کی وسعت اور تنوع پر زور دینے کے باوجود اسے’ حقیقی اور سچی شاعری‘ قرار دیتے نظر نہیں آتے۔ ان کے لیے قومی شاعری ہی حقیقی اور سچی شاعری ہے۔
سر عبدالقادر کی طرح حالی کوبھی اردو میں قومی شاعر نہ ہونے کی فکر تھی۔ ظاہر ہے یہ فکر انگریزی شاعری کے اس اثرنے پیدا کی تھی جسے سر عبدالقادر نے براہِ راست اور حالی نے بالواسطہ مگر کہیں زیادہ شدت سے قبول کیا تھا۔ اپنے دیوان کا مقدمہ بہ عنوان ’شعر و شاعری پر‘لکھتے ہوئے وہ اردو شاعری میں قومی شاعر کی تلاش کرتے اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں:
’’لکھنئو میں میر انیس اور مرزا دبیر نے بھی تقریباً ایسی ہی قبو لیت حاصل کر لی تھی۔ جو لوگ میر انیس کو پسند کرتے تھے،وہ مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں جہاں تک ہو سکتا تھا،میر انیس کی تقلید کرتے تھے اور جو فریق مرزا دبیر کا طرف دار تھا، وہ ہر ایک بات میں ان کی پیروی کرتا تھا،مگر لارڈ بائرن اور ان دونوں صاحبوں کی قبولیت میں اتنا بڑا فرق ہے کہ لارڈ بائرن کی عظمت اہلِ فرنگ کے دل میں اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کو اپنا قومی شاعر سمجھتے تھے اور اسی لیے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں فرقے اس کو یکساں عزیز رکھتے تھے،بخلاف انیس و دبیر کے کہ ان کی عظمت محض ایک مذہبی شاعر ہونے کی وجہ سے تھی اور اسی لیے ان کی بڑائی اور بزرگی جیسی کہ عموماً ایک فرقہ کے دل میں تھی،ویسی عام طور پر دوسرے فرقہ کے دل میں نہ تھی۔ یہ امتیاز قومی اور مذہبی حیثیت کا ہمارے اور اہلِ یورپ کے تمام کاموں میں پایا جاتا ہے۔‘‘ ۹
مولانا حالی نے قومی شاعر اور قومی شاعری کا کم و بیش وہی تصور قائم کیا ہے جو سر عبدالقادر کے یہاں تھا۔ یہ کہ قومی شاعر قومی وحدت پیدا کرتا ہے اور قومی شاعری پیدا کرنے کے لیے یورپی شاعری کو مثال بنا نا چاہیے۔ نیز ہماری ادبی تاریخ میں یورپی طرز کے قومی شاعرکا وجود نہیں۔ تاہم حالی نے قومی شاعری کے حوالے سے کئی اور باتیں بھی کَہ ڈالی ہیں۔ ایک یہ کہ ’’قوم‘‘ میں شاعری کی مقبولیت، شاعری کے قومی ہونے کی ضمانت نہیں۔ شاعری کا یہ قومی کردار بالکل نیا تھا۔ اس سے اردو شاعری نا آشناے محض تھی۔ حالی کا قومی زاویۂ نظرانھیں اس سمت متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ’قومی تصور کے بغیراردو شاعری‘وسیع المشربی کی حامل تھی۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی ایک فرقے کے خلاف یا اس کی حمایت میں تھی۔ اصل یہ ہے کہ اس میں فرقے کا تصور موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تفریق و تقسیم کے مذہبی،نسلی تصور سے ماورا تھی،اس لیے ہم کَہ سکتے ہیں کہ وہ اگر اتحاد پروری کو اپنا مقصود اصلی نہیں بناتی تھی تو، ہندو، مسلم اور برہمن و شودر میں تفریق کرنے کا کوئی اشارہ تک نہیں دیتی تھی۔ اس شاعری کا اگر کوئی ہدف تھا تو رسم پرستی اور اس کے علم بردار تھے۔ اس میں شیخ و بر ہمن ، زاہد وملا میں تفریق نہیں تھی۔ علاوہ ازیں حالی لارڈ بائرن کی مدح میں یہ بھول گئے کہ وہ ان کے قومی شاعر ہونے کی جو دلیل لارہے ہیں وہ خود ان کے دعوے کی تردید کرتی ہے۔ بہ قول حالی بائرن کیتھولک اور پروٹسنٹ دونوں فرقوں میں مقبول ہیں۔ مان لیا۔ کیا یہ دونوں مذہبی فرقے نہیں ہیں؟کیا حالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود اہلِ یورپ قومی شاعر کے ضمن میں متحد تھے اور اردو میں ہمیں اس نوع کا اتحاد نظر نہیں آتا؟نہیں معلوم حالی اس بدیہی بات کو کیوں بھول گئے کہ انیس اور دبیر تو ایک ہی مذہبی فرقے کی شاعری کرتے تھے اور ان کے مداح جن دو طبقوں،انیسیوں اور دبیریوں میں منقسم تھے وہ مذہبی بنیاد پر نہیں،شعری بنیاد پر تھے۔ جہاں تک جارج گورڈن بائرن(۱۷۸۸ء-۱۸۲۴ء)کے قومی شاعر ہونے کا سوال ہے تو عرض ہے کہ نسلاً نصف انگریز اور نصف سکاٹ، بائرن حقیقی معنوں میں قومی کی بجائے ’’بین الاقوامی رومانی شاعر‘‘ تھا۔ اسے یورپ کے کئی ملکوں،سپین،سوئٹرزلینڈ،اٹلی وغیرہ میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ لوئی کزامیا کے بہ قول وہ پہلا شاعر تھا جس نے یورپ کو متاثر کیااور اس کے ادب پر وسیع اثرات مرتب کیے۔(۱۰) اگر حالی بائرن ہی کی مثال کو، اس کے درست سیاق کے ساتھ پیشِ نظر رکھتے تو انھیں پندرھویں صدی کے کبیر داس کوقومی شاعر تسلیم کرنے میں تامل نہ ہوتا کہ اس نے مسلمان صوفیوں اور ہندو سنتوں کا اثر قبول کیا تھا اور اس کی شاعری نے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں، اپنی انسان دوست اور وحدت آشنا شاعری کے سبب غیر معمولی مقبولیت حاصل کی تھی۔ مگر اس امر کی حالی کے قومی شاعری کے اس تصور میں گنجائش ہی نہ تھی جس کی روشنی مغربی لالٹینوں سے مستعار تھی۔
حالی نے قومی شاعری کی کسوٹی سے یورپ اور برعظیم میں امتیاز بھی کیا ہے۔ یورپ میں قومی شاعری ہے، اس لیے وہاں اتحاد و اتفاق ہے اور اردومیں قومی شاعری نہیں،اس لیے اتحاد نہیں۔ اب اتحادکی ضرورت سے کس کافر کو انکار ہو سکتا ہے اوریہیں قومی شاعری کی گنجائش خود بہ خودنکل آتی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حالی انیسویں صدی کے عمومی یورپی تصور کے عین مطابق برعظیم کی شناخت میں مذہب اور یورپ کی شناخت میں قوم کے تصو ر کو مرکزیت دیتے ہیں۔ اب چوں کہ یورپ کی طرز پر برعظیم کی اصلاح مطلوب ہے لہٰذا قومی شاعری چاہیے۔ اس طور دیکھیں تو اردو میں قومی شاعری کی ’تحریک‘ وراے شعری تحریک تھی۔ اس کی بنیاد قوم کے ایک ایسے تصور پر تھی جو خود مغرب میں انیسویں صدی میں ایجاد ہوا تھا۔
٭
اردو میں قومی شاعری کی ابتدائی مثالیں، قومی شاعری پر شروع ہونے والے باقاعدہ ڈسکورس سے پہلے یعنی انجمنِ پنجاب کے موضوعاتی مشاعروں میں سامنے آئیں۔ موضوعاتی مشاعرے اس اصلاحی منصوبے کا حصہ تھے،جو اردو شاعری کو مبالغے، خیالی طوطا مینااور ان نیچرل عناصر سے ’پاک‘ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ بہ قول حالی ’’ اس مشاعرے کا مقصد یہ تھا کہ ایشیائی شاعری جو کہ درو بست عشق اور مبالغے کی جاگیر ہو گئی ہے اس کو جہاں تک ممکن ہو وسعت دی جائے اور اس کی بنیاد حقائق اور واقعات پر رکھی جائے۔‘‘(۱۱) ۱۸۷۴ء کے مشاعرے کا موضوع ’’حب وطن‘‘ تھا۔ اس موضوع کو ان مشاعروں کے دیگر نیچرل موضوعات ہی کی طرح ایک نیچرل موضوع کے طور پر تجویز کیا گیا تھا۔ گویا ’حب وطن‘امید، برسات کی طرح ایک ایسا مقامی فطری موضوع تھا جو اردو شاعری کو اس کی پابستہ فضا سے آزادی دلا سکتا تھا۔ اس مشاعرے میں حالی نے بھی نظم پڑھی۔ اردو شاعری میں یہ غالباً پہلی نظم ہے جس میں قوم کا تصور تشکیل دینے کی کوشش ملتی ہے۔ غور کریں تو حبّ وطن، اردو شاعری کے لیے یک سر نیا اور اجنبی موضوع نہیں تھا،کلاسیکی شاعری میں اس موضوع پر کچھ غیر معمولی اشعار موجود تھے، جیسے وحید الہٰ آبادی کا یہ شعر:ہم نے جب وادیِ غربت میں قدم رکھا تھا /دور تک یادِوطن آئی تھی سمجھانے کو۔۔۔ مگر حالی کی نظم میں وطن کی محبت کے عین فطری جذبے کو ایک آدرش میں بدلنے کی سعی ملتی ہے۔
بینڈکٹ اینڈرسن نے کہاہے کہ قوم مشترک زبان،نسل،مذہب اور تاریخ جیسے عمرانیاتی عوامل کی لازمی پیداوار نہیں[جیسا کہ انیسویںصدی میں سمجھا گیا تھا]بلکہ’’ متخیلہ میں تشکیل دیا گیا سیاسی گروہ‘‘ ہے۔(۲ ۱) مابعد نو آبادیاتی مطالعات میں قوم اور تخیل کے باہمی تعلق پر خیال انگیز بحثیں ہوئی ہیں۔ یہ بحثیں زیادہ تر اس نکتے کے گرد گھومتی ہیں کہ ذرائع ابلاغ اور ادب اپنے قارئین کے تخیل میں ان کی اجتماعی قومی شناخت کاتصور قائم کرتے ہیں۔ چناں چہ انیسویں صدی میں قوم کے تصورات اور قومیت پرستی کی تحریکیں اس وقت فروغ پذیر ہوئیں جب اخبارات اورناول عام ہوئے۔ اخبارات اور ناولوں نے ’واقعات ِدہر ‘ یا تاریخ کومتسلسل وقت کی پیداوار بنا کر پیش کیا،جس سے قارئین کے یہاں ’اپنی‘ تاریخ کا مسلسل تصور اور اسی کے نتیجے میں اپنی شناخت کا تخیل پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس قومی تخیل میں مذہب، نسل، جغرافیہ یا زمین اور زبان ضرور شامل تھے، مگر یہ سب یا ان میں کوئی ایک،قومی تخیل کو پیدا نہیں کرتے تھے، اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ بہر کیف ا ن بحثوںمیں قوم کا تعلق عام انسانی تخیل سے جوڑا گیا ہے، جو ایک منفعل، باہر کے وقوعات سے اپنی صورت اور نہج حاصل کرنے والی انسانی صلاحیت ہے۔ نیز یہی وہ صلاحیت ہے جوسماجی اور سیاسی’طاقت کے کھیل ‘کا آلۂ کار بن جایا کرتی ہے۔ ان بحثوں میں تخلیقی تخیل کا ذکر نہیں ہے جوعام انسانی تخیل کی طرح منفعل نہیں،بلکہ فعال ہے اور یک سر نئی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے؟علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ’’قومیں شاعروں کے تخیل [دل] میں جنم لیتی اورسیاست دانوں کے ہاتھوں میں پھولتی پھلتی اور مرجاتی ہیں۔‘‘ (۱۳) ہر چنداس مقولے میں اقبال قوم کی تخلیق کو شعری تخیل سے منسوب کر کے، سیاست دانوں کے افلاسِ تخیل پر افسوس کا اظہار کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم ایک اہم نکتہ انھوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قوم اس تخیل کی پیداوار نہیں جو محض نظروں سے اوجھل نامعلوم کو معلوم بنا کر پیش کرتا ہے یا مبہم کو واضح کرتاہے بلکہ اس تخیل سے قوم جنم لیتی ہے جو’’ایک زندہ قوت اور تمام انسانی ادراک کا سب سے اہم عامل ہے اور محدودانسانی ذہن میں تخلیق کے ابدی عمل کا اعادہ ہے‘‘۔(۱۴)چناں چہ اقبال قوم کوایک سیاسی تصور کے بجائے تخلیقی تصور قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا شاعر کا تخیل فی نفسہ آزاد ہوتا ہے اور وہ قوم کا تصور اپنی اسی وجودی آزادی کو بروے کار لاتے ہوئے وضع کرتا ہے یا شاعر کا تخیل اپنے عہد کی سماجی صورتِ حال کا پابند ہوتا ہے؟
اس سوال کا ایک جواب حالی کی ’’حب وطن‘‘ کے مطالعے سے مل سکتاہے۔
اس نظم میں وطن سے محبت کی دو صورتوں کا ذکر ہے:حیوانی/ جبلی اور انسانی/تخیلی۔ حالی جب یہ کہتے ہیں: جن و انسان کی حیات ہے تو/ مرغ و ماہی کی کائنات ہے تو؛ہے نباتات کو نمو تجھ سے/ روکھ تجھ بن ہرے نہیں ہوتے۔۔۔تو وطن سے محبت کی اس جبلی سطح کا ذکر کرتے ہیں جوانسان سمیت تمام جانداروں میں یکساں ہے۔ یہ محبت دراصل اپنی جنم بھومی سے ہے۔ لہٰذا یہاں وطن سے مراد’’گھر‘‘ ہے۔ اس کے لیے نباتاتی تمثال ہی موزوں ہے۔ آدمی کا اپنے ’’گھر‘‘سے وہی گہرا تعلق ہوتا ہے جو پودے کا اپنی مٹی سے ہے۔ مٹی پودے کی ماں ہے۔ ماں، نباتاتی تمثال کامخفی مگر ناگزیر پہلو ہے۔ ’’گھر‘‘ ماں سے خالی نہیں ہوتا اور ہر ماں کوئی نہ کوئی زبان بولتی ہے۔ چناں چہ وطن سے یہ محبت دراصل اپنی مٹی،ماں اور مادری زبان سے فطری محبت ہے۔ یہ محبت اس وقت اپنی پوری قوت سے بیدار ہوتی ہے جب آدمی گھر سے دور ہوتا یا اسے گھر سے جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بحران ہی وطن کا تصور پوری شدت سے اجاگر کرتا ہے۔ حالی نے اس شعر میں اسی بحران کی طرف اشارہ کیا ہے: جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا /کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں بھی تمثال مادی اور جسمانی ہے۔ بحران کے لمحے میں آدمی اس’’گھر‘‘ پر مرکوز ہوکر رہ جاتا ہے جو حقیقتاًمحدود، نجی اور اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اسی لیے اسے ایک اپنی قسم کا بہشت بریں کہا جاتا ہے،حال آنکہ یہ ایک مشت خاک ہے (تیری اک مشتِ خاک کے بدلے/ لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے)۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں تخیل کا عمل دخل شروع ہوتا ہے۔ بحران کی حالت میں، گھر سے دور رہ کر’’گھر‘‘ تک رسائی کا ذریعہ تخیل بنتاہے۔ یہ ’’گھر‘‘ کی بازیافت ہے۔ ایک تخلیقی عمل ہے۔ ایک اوڈیسی ہے۔ تو کیا حالی بین السطور یہ کَہ رہے ہیں کہ وہ ’’اپنے ہی گھر‘‘ میں رہتے ہوئے، اپنے گھر سے دور ہیں؟وہ لاہور میں رہتے ہوئے پانی پت کی مشت خاک کو بہشت سے افضل قرار دے رہے تھے؟یا ہندوستان میں رہتے ہوئے خود کو ہندوستان سے باہر اور دور تصور کر رہے تھے؟اس سوال کا جواب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ہم یہ طے کرنے میں کام یاب ہوں کہ اس نظم کا متکلم کون ہے؟حالی یا ایک ہندوستانی؟دل چسپ بات یہ ہے کہ نظم کے متکلم پر نہ تو حالی پانی پتی کا گمان ہوتا ہے نہ ایک ایسے ہندوستانی کا جو اپنے ہی وطن میں غریب الدیار ہو گیا ہو۔ نظم کا متکلم ایک ’نیا شاعر ‘ہے اور وہ ایک ’نئی تخیلی کمیونٹی‘ کو مخاطب ہے۔ حالی جب تک حبّ وطن کی جبلی سطح کا شعری بیان جاری رکھتے ہیں، وہ ایک شاعر ہیں،مگر جب گریز کرتے ہوئے کہتے ہیں:
کہیے حبّ وطن اسی کو اگر
ہم سے حیواں نہیں ہیں کچھ بد تر (۱۵)
تو وہ ایک ’نئے شاعر‘ کا تکلم اختیار کرتے ہیں۔ ’نیا شاعر ‘حیوانی اور انسانی سطحوں کی اس حد فاصل میں ’قومی شعری بیانیہ‘ وضع کرتا ہے،جسے انیسویں صدی کے اواخر میں پوری طرح واضح تصور کرنا آسان تھا۔ تب چیزوں کو تفریقی رشتوں کے ذریعے سمجھنا ہی مقامی فکر کا معمول تھا۔ یہ عین وہی تفریقی تصورہے جو ہندوستان اور یورپ میں فرق کرتا ہے۔ یہ حد فاصل ایک نیا ذہنی اور تخیلی عرصہ ہے،جس میں حب وطن کے جبلی میلان کو حیوانی قرار دے کر تضحیک کا نشانہ بنا یا گیا ہے اور اس کے مقابل ’آدمی‘ کی ایک نئی تعریف وضع کی گئی ہے۔ یہ تعریف وجودی ہے نہ جوہری،اسے زیادہ سے زیادہ ثقافتی قرار دے سکتے ہیں،بشرطے کہ نئی ابھرتی ہوئی ثقافت ہمارے پیشِ نظر ہو۔ یعنی ’آدمی ‘وہ ہے جو اپنے وجود کے مطالبات سے دست بردار ہوکر اپنے وجود کو ’قوم‘ کے لیے مختص کردے یا اس کے وجود کے مطالبات اور’ قوم‘کے مطالبات میں کوئی دوئی باقی نہ رہے۔ اردو شاعری میں آدمی کا یہ ایک نیا تصور تھا۔ اردو کا شاعر آدمی کا یہ تصور کرتا تھا:
بے خودی لے گئی کہاں ہم کو
دیر سے انتظار ہے اپنا
اس بت کدے میں معنی کا کس سے کریں سوال
آدم نہیں ہے صورتِ آدم بہت ہے یاں
بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا
آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
یہ ’آدمی‘ اپنے وجود اور جوہر کا اظہار صوفیانہ اور نیم فلسفیانہ پیرائے میں کرتا تھا۔ وہ اپنے ’اندر‘ ایک ایسی آزادی اور ایک ’نجی عرصہ‘ محسوس کرتا تھا،جو اسے وجود کے بنیادی سوالات پر ارتکاز کرنے کے قابل بناتے تھے۔ اس ’آزادی ‘کی راہ میں سماجی زندگی حائل نہیں ہوتی تھی۔ یعنی سماجی زندگی کی طرف سے شاعر پر خاص موضوعات پر لازماً لکھنے کا دباؤ نہیں تھا۔ سماجی اور اجتماعی زندگی کا ’مقام و مرتبہ‘ متعین تھا، لہٰذا وہ اپنی حد میں رہتی تھی۔ اس بنا پر آدمی کو وجود کی معنویت پر تفکر کرنے اورمعنویت کے ہاتھ آنے پر ایک خاص کیف و سرشاری کا تجربہ کرنے اورناکامی پر کفِ افسوس ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ گویا آدمی کے تعلق میں اس کا تخیل صوفیانہ اور فلسفیانہ سرحدوں سے منسلک تھا۔ مگر ’نیا شاعر‘ان سرحدوں کو خیالی اور ان نیچرل تصور کرتا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں بھی تفریقی فکر کام کر رہی ہے۔ یہ فکر محض چیزوں کو فرق کی بنیاد پر ہی نہیں سمجھتی تھی،ان میں لازماً درجہ بندی بھی قائم کرتی تھی۔ ’قومی تصور کے بغیر اردو ادب‘کی خیالی اور ان نیچرل دنیا،نئی مادی اور حقیقی دنیا کے مقابلے میں فرو تر تھی۔ دو دنیاؤں کی درجہ بندی، ایک کے انتخاب اور دوسری کے ردّ کو آسان اور معقول بنا دیتی تھی۔ لہٰذا ’نیا شاعر‘اس مادی حقیقت سے آدمی کی جاں نثارانہ وابستگی پر زور دے رہا تھا،جس کا مادی ہونا اشکالیہ (Problematic)تھا: یہ حقیقت مادی ہونے کے دعوے کے باوجود حسیات سے از خودگرفت میں نہیں آتی تھی؛اس کا تخیل قائم کرنا پڑتا تھا۔ اقبال نے مولانا حسین احمد کے مضمون ’’اسلام اور نیشنل ازم‘‘ (مطبوعہ ’’احسان‘‘ ۹مارچ ۱۹۳۸ء) پر ردّعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ’’ اپنی جنم بھومی سے محبت فطری جبلت ہے اور اس کی پرورش کے لیے اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں‘‘۔ (۱۶) لیکن جب اس پر زور دیا جانے لگے اور گھر کی مشت خاک کی محبت کو قوم پرستی میں گوندھنے پر اصرار کیا جانے لگے تو اس کا مطلب گیاتری چکر ورتی کے مطابق ’’انتہائی نجی چیز کو عوامی‘‘(۱۷)بنانے کا عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی کے مغربی انسان کے دماغ میں ایک نیا گومڑنمودار ہوا،جس نے قوم پرستی کا تخیل قائم کیا۔ وہیں سے نو آبادیاتی اثرات میں لپٹا ہوا ہمارے یہاں پہنچا۔ ہمارا ’نیا شاعر‘ اسی قومی تخیل کے تحت ’صحیح آدمی‘کے خدو خال ابھارتا ہے۔
جس پہ اطلاقِ آدمی ہو صحیح
جس کو حیواں پہ دے سکیں ترجیح
قوم سے جان تک عزیز نہ ہو
قوم سے بڑھ کے کوئی چیز نہ ہو (۱۸)
حالی کی نظم میں یہاں تک’ صحیح آدمی‘ کا تصور تو واضح ہو جاتا ہے،مگر قوم کا نہیں۔ روایتی طور پر قوم، باپ سے شناخت کیے جانے والے خاندان کے معنوں میں رائج تھاجو وسیع ہوکر پہلے قبیلے اور بعد میں اس عصبیت میں بدل جاتا تھا جس پر ابنِ خلدون نے قوم اور سلطنت کے تصور کی بنیاد رکھی تھی،مگر یہاں حالی ایک نئی ’تخیلی اکائی ‘کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قوم کا ابتدائی تصور حالی نظم‘‘ پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ‘‘ میں متعارف کرواتے ہیں :
قوم کی تعریف نہیں جانتے
اپنی حقیقت نہیں پہچانتے
کر نہیں سکتے وہ حقائق میں غور
کہتے ہیں جڑ اور ہے ٹہنی ہے اور
جانتے دریا کو ہیں اک شے جدا
قطروں سے کہتے ہیں کہ وہ ہے جدا
پر یہ عزیزوں کو نہیں سوجھتا
ہے انھیں قطروں سے وہ دریا بنا(۱۹)
وطن کی مشت خاک کے بدلے بہشت بریں قبول نہ کرنے والے، قوم کی تعریف کیوں نہیں جانتے؟ وجہ یہ نہیں کہ نظم کے تخیلی مخاطب غبی یا خود غرض ہیں،بلکہ یہ کہ حالی ان کے سامنے ایک نئی چیز کا تخیل پیش کر رہے تھے۔ اس کے لیے حالی مانوس تمثالیں استعمال کر رہے ہیں۔ نظم کے معلمانہ اسلوب کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ ابتدا تا آخر بیّن ہے۔ بلاشبہ اچھی شاعری کے لیے یہ اسلوب ہر گز روا نہیں،مگر قومی شاعری کی ابتدائی مثالوں کے لیے اس سے بہتر اسلوب کی توقع ہی غیر مناسب ہے۔ اس کے باوجود یہ نظم غیر معمولی داخلی وحدت رکھتی ہے۔ نظم کی تمثالیں،نظم کے خیالات اور ان کے ارتقا سے گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ ابتدا میں حالی وطن کی جبلی محبت کے لیے نباتاتی تمثال استعمال کرتے ہیں اورنظم کے آخر میں ’قوم کی انسانی محبت ‘کا تصور اجاگر کرنے کے لیے اس تمثال کی جگہ دریا کی متحرک تمثال لاتے ہیں۔
ہمارا ’نیا شاعر‘ اپنے تخیلی مخاطبین کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی حقیقت ’قوم‘ سے ہے۔ لہٰذا قوم کو سمجھنے کا مطلب خود ہی کو سمجھنا ہے۔ چوں کہ ’نئے شاعر‘ کے نزدیک قوم ایک مادی حقیقت ہے، اس لیے وہ اسے واضح کرنے کے لیے ٹھوس اور مادی تمثالوں ہی پر انحصار کرتاہے۔ وہ اپنے مخاطبین کی یہ دلیل قبول نہیں کرتاکہ ٹہنی اور جڑ کا تعلق دو مختلف منطقوں سے ہے۔ جڑ،داخلی، نجی، محدود اور پھر اتنی ہی مضبوط ہے، جب کہ ٹہنی خارجی،پھیلی ہوئی اور اسی قدر کم زور ہے۔ ٹہنی، جڑ کا ’عوامی منطقہ‘(Public sphere)ہے۔ اگرحالی اسی تمثال کو برقرار رکھتے تو گویا تسلیم کرتے کہ عوامی منطقے سے رسم وراہ فرد کی نجی زندگی کے احترام و استحکام کی شرط کی بنیاد پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ وطن کی فطری محبت ہی کا دائرہ پھیلا کر قوم کے عشق کا تصور پیش کرتے۔ مگر یہ تفریقی رشتوں کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کی معاصر روش کے خلاف اقدام ہوتا۔ حالی معاصر حاوی روشوں کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے (چلو تم ادھر کو ہواہو جدھر کی)۔ چناں چہ وہ نباتاتی اور دریائی تمثالوں کے فرق سے قوم کا تصور واضح کرتے ہیں۔ اس بات پر بار دگر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ نباتاتی تمثال، حالی کے لیے حیوانی زندگی کی علامت ہے۔ اسی نسبت سے دریا انسانی زندگی کی۔
فرد کو قطرہ اور قوم کو دریا فرض کرنا،محض ایک شعری تمثال نہیں۔ یہ فقط ایک مجرد خیال کو مجسم بنا کر، ایک نیم واضح بات کو حسّی اور مانوس پیرائے میں پیش کرنے تک محدود نہیں۔ یہ تمثال اردو شاعری میں ایک داخلی معنیاتی سطح کی مکمل جست کی نمایندہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نمایندگی کی سطح پر بھی یہ تمثال مکمل ہے۔ دیکھیے:قطرے اور دریا کی تمثال اردو شاعری کے لیے نئی نہیں ہے،مگر اسے نئے مفہوم میں استعما ل کیا گیا ہے۔ نامانوس اور نئے تخیل کو مانوس اور پرانے فارم میں اس طور استعما ل کرنا کہ دونوں میں تفریقی رشتہ قائم ہو،یہ حالی کی قومی شاعری کی ممتاز خصوصیت ہے۔ حالی کے استاد اور ممدوح مرزا غالب یہی تمثال استعما ل کر چکے ہیں:
قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
ہم کو منظور تنک ظرفیِ منصورنہیں
قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل
کھیل لڑکوں کا ہوا دیدۂ بینا نہ ہوا
یہاں قطرہ اور دریایعنی جزو اور کل، وحدت الوجودی تصوف کی مرکزی علامتیں ہیں۔ وجودی تصوف میں کل یا دریااس ہستیِ مطلق کی علامت ہے جو ہر جگہ،ہر وقت موجود ہے۔ قطرے کا دریا یا جزو کا کل سے الگ ہونا، التباس ہے۔ دونوں دراصل ایک ہیں، اور ’’ایک ‘‘ ہونے کا انکشاف دیدۂ بیناہی کر سکتی ہے۔ (گویا اردو شاعری کی حکمت اور دانائی مابعد الطبیعیاتی حقیقت کے کشف سے عبارت ہے۔)حالی بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قطرے اور دریا کا الگ ہونا، التباس ہے۔ اس التباس کا پردہ بھی ’’دیدۂ بینا‘‘ ہی چاک کر سکتی ہے،مگر اس فرق کے ساتھ کہ پہلے دیدۂ بینا ذاتی، نجی تھا،اب عوامی ہے۔ ’نیا شاعر‘ اسی دیدۂ بینا یا نئے تخیل کا ترجمان ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا ’نئے شاعر‘ کا دیدۂ بینا اس وجدان کی کارکردگی کا کوئی نیا اسلوب ہے جو فطری طور پر اسے عطا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ شاعر ہوتا ہے یاکوئی دوسری بات ہے؟اوّل تو’نئے شاعر‘ کے تخلیقی عمل کی وضاحت کے لیے وجدان کا لفظ ہی غیر موزوں ہے۔ وجدان سے ایک نوع کا مابعد الطبیعیاتی مفہوم وابستہ ہے جو اسے ’مادی، عوامی،سماجی‘دنیا سے ماورایا کم از کم اس دنیا کے حسی اثرات سے آزادقرار دیتا ہے۔ جب کہ ’نئے شاعر ‘ کی کل کائنات یہی ’مادی ،عوامی،سماجی‘دنیا ہے۔ لہٰذا اب شاعر کا دیدۂ بینا بھی ’مادی،عوامی اور سماجی‘ ہے۔ اس کا شاعر ہونا، اسی دنیا اور اس کے معاملات و مسائل سے وابستہ ہونے میں ہے۔ چناں چہ ایک نوع کے مابعد الطبیعیاتی منطقے سے منسلک ہونے میں شاعر کو جو داخلی آزادی حاصل تھی، نیا شاعر اس سے محروم ہے۔ اس کے تخیل کی کائنات عوامی منطقے سے تعمیر ہوتی ہے۔ اس منطقے سے باہرجھانکنااس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے مگر باہر بھی اسی عوامی منطقے کے مفصلات ہیں۔ خود ’’باہر‘‘ کا تصورسماجی ہو گیاہے۔ لہٰذایہ کہنا صرف ایک امر واقعہ کااظہارکرنا ہے کہ حالی کا پیش کردہ تصور قوم،ان کے عہد کی حاوی سماجی قوتوں کا تشکیل کردہ ہے۔ حالی اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ’نیا شاعر ‘ اپنا نیا منصب دریافت کرتا ہے: قوم کی راہ نمائی،مگر اس راہ کا پہلا سنگِ میل قوم کا تصور واضح کرنا اور باور کرانا ہے۔ اقبال تک پہنچتے پہنچتے ’نیا شاعر‘اس سفر کا دائرہ مکمل کر لیتا ہے،جس کا آغاز حالی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اتفاق نہیں کہ اقبال فرد اور قوم کے رشتے کا تصور ٹھیک اسی تمثال میں پیش کرتے ہیں جو حالی نے برتی ہے:
فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں
ممکن ہے کوئی اس فرق کی نشان دہی کرے کہ اقبال یہاں قوم نہیں ملت کی بات کر رہے ہیں۔ حالی کی شعری لغت میں ملت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،کہیں قوم اور کہیں ایک مذہبی شناخت کے حامل سماج کے مفہوم میں۔ نظم ’پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ ‘ ہی میں کہتے ہیں:
قوم میں جو دیکھیے چھوٹا بڑا
چنتا ہے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد جدا
سوجھتی ملت کی نہیں کوئی بات
یہ جو کہے دن تو وہ کہتا ہے رات(۲۰)
٭
سیاسی سیاق میں قوم کا تصور کافی پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے۔ اپنی سادہ صورت میں یہ کسی گروہ انسانی کی اجتماعی شناخت ہے،مگر اس شناخت کی بنیادکیا ہے اور اس کے تشکیلی عناصر کیاہیں، یہ سوالات اسے پیچیدہ بنادیتے ہیں۔ قوم کی بنیاد عام طور پر نسل، جغرافیہ، زبان اور مذہب تصور کیے گئے ہیں۔ یہ تمام انسانی گروہوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی موجود تھے جب قوم اور قوم پرستی کے نظریات اور تحریکیں سامنے نہیں آئی تھیں۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ یہ از خود قوم کی تشکیل نہیں کرتے۔ قوم کی تشکیل میں انھیں، دست یاب مواد کے طور پر، بروے کار لایا جاتا ہے۔ سو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ قوم کا تصور ایک تشکیل،ایک تخیل اورایک ’کنسٹرکٹ‘ ہے ؛کوئی عنصر فطری طور پر اس کی تہ میں موجود نہیں ہوتا۔
قوم کے ہرتصور میں،فرق اور دوئی لازماً موجود ہوتے ہیں،خواہ اس کی بنیاد مذہب،زمین،زبان یا نسل کچھ بھی فرض کیا جائے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ’غیر ‘ہوتا ہے۔ قوم ایک تصور کے طور پر ا س’غیر‘ کے مقابل اپنی بنیادیں واضح کرتی ہے اور ایک حقیقت کے طور پر اپنے ’غیر‘ کے مقابل اپنے بلند اور عظیم آدرش وضع کرتی ہے۔ فرداپنے لغوی اور استعاراتی مفاہیم کے ساتھ، قوم کا غیر ہے۔ فرد کی ایک الگ شخصی وجود کے طور پر اثبات کی کوئی بھی کوشش، اس ’’تخیلی وجود‘‘ کے لیے خطرے سے کم نہیں ہوتی،جسے قوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا غور کریں تو قوم کا تصوروضع اور واضح کرنے کے لیے قطرے اور دریا کی تمثیل سے بہتر کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی۔ یہ تمثیل فرق کاشدید احساس پیداکرکے اسے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ قطرے اور دریا میں فرق کس قدر زیادہ ہے،یہ ظاہر ہے۔ تاہم اس فرق کو مٹانے کی کوشش بھی توجہ طلب ہے۔ کلاسیکی شاعری میں قطرے اور دریا کے فرق و فاصلے کے مٹانے کی صورت یہ تھی کہ قطرہ،اپنے اندر ہی دریا کا مشاہدہ کر لیتا تھا،مگر ’نیا شاعر‘ایک ایسے دریا(قوم) کا تخیل ابھارتا ہے، جس میں قطرہ(فرد)خود کو فنا کردے۔ اپنے وجود کو اس کی امانت تصور کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب دریاسے مقدس ہونے کی کوئی متھ وابستہ ہو۔ یہاں قوم پرستی کا نظریہ مذہب اور اساطیر سے کافی کچھ مستعار لیتا ہے۔
لطف کی بات یہ ہے کہ جن عناصر کو قوم کے تشکیلی اجزا تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے ’غیر‘ بن سکتے ہیں۔ تاہم خاطر نشان رہے کہ مذہب، زبان، زمین،نسل میں ایک دوسرے کا ’غیر‘ بننے کا میلان نہیں ہوتا۔ جب ان میں سے کسی ایک یا زیادہ عناصر کو قوم کی اساس بنایا جاتا ہے تو ان سب میں ایک قسم کی درجہ بندی وجود میں آجاتی ہے۔ یعنی یہ سب ایک درجہ بند نظام میں شامل ہوجاتے ہیں۔ ایک یا دو عناصر بے حد روشن اور واضح اور دوسرے نیم واضح، مدھم ہوجاتے ہیں۔ روشنی اور تاریکی کا یہ تقابل، جو اوّل اوّل محض ادراک یا تخیل کی سطح پرہوتا ہے،جلد ہی علامتی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ مذہب،نسل، زمین یا نسل محض ایک سادہ تصور نہیں رہ جاتے،وہ جب کسی قوم کی بنیاد بنتے ہیں تو کئی باتوں، آدرشوں کی نمایندگی کرنے لگتے ہیں اور اس راہ میں خود سے مختلف عناصر کو راستے کے سنگ گراں کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہر قوم کا فقط ایک ’غیر‘ ہی نہیں ہوتا،وہ اس سے نبرد آزما بھی ہوتی ہے۔ قومیت پرستی کی کوئی تحریک ایسی نہیں،جس میں خود سے مختلف قوموں سے نظریاتی یا حقیقی جنگ نہ کی گئی ہو۔
حالی کی قومی نظموں میں ’غیر‘کا تصور ابتدا ہی سے موجود ہے،تاہم یہ ایک نہیں۔ دراصل حالی کی قومی نظمیں، ان کے تصوراتِ قوم کے ’ارتقا‘ کی علامت بھی ہیں،اس لیے ان کے قومی تصور میں تبدیلی کے ساتھ ہی ’غیر‘ کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ حالی کی قومی نظموں کو ہم قوم اور قومیت پرستی کے عمومی کلامیے (General Discourse) کے طور بھی پڑھ سکتے ہیں ۔ قومیت پرستی کا کلامیہ، اجتماعی قومی شناخت کے لیے ’مرکز‘کی دریافت سے عبارت ہوتا ہے۔ اس کلامیے کا سب سے دل چسپ پہلو یہ ہے کہ وہ جسے ’مرکز‘ قرار دیتا ہے،وہ معروضی نہیں،تخیلی ہوتا ہے؛ایک تشکیل ہوتا ہے۔
’حبّ وطن ‘ میں’ غیر‘کا ایک واضح اور ایک مبہم تصور بیک وقت ہے۔ ابتدا میں حالی کے یہاں تفرقہ،ایک واضح ’غیر‘ہے جسے وہ ایک قوم کے لیے سم قاتل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گویا یہاں ہندوستانی قوم کا مرکز ہندوستان کی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین،ہندوستانی قوم کا مرکزی تنظیمی اصول ہے۔ مسلمان، ہندو، بودھ، جینی(عیسائی،پارسی،سکھ)اور ان کے ذیلی فرقے، قطرے ہیں، جو ’وطنیت کے دریا ‘ کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک دوسرے کا’ غیر ‘ نہیں ، ان کا اگر کوئی ’غیر‘ اور مد مقابل ہے،جو انھیں ایک ہونے سے روکتا ہے تو وہ ’’تفرقہ‘‘ ہے۔ اپنی نظم ’’پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ‘‘ میں وہ پھوٹ اور تفرقے کو باہمی اختلافات کے معنی میں استعمال کرتے ہیں:
تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر
نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر
ہو مسلمان اس میں یا ہندو
بودھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمو
جعفری ہووے یا کہ ہو حنفی
جین مت ہووے یا ہو بیشنوی
سب کو میٹھی نگا ہ سے دیکھو
سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو(۲۱)
حالی جب زمین کو قوم کی اساس تسلیم کر لیتے ہیں تو،قوم کے پیچیدہ تصور کا ایک آسان حل دریافت نہیں کرتے(جیساکہ بہ ظاہر محسوس ہوتا ہے)اس کی پیچیدگی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جب وہ زمین کو قوم کا مرکزی تنظیمی اصول سمجھتے ہیں تویہ ایک سادہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں۔ حالی کی قومی شعری فکر میں یہ ایک بے حد اہم لمحہ ہے۔ یہیں ان کا تاریخی شعور بیدار ہوتا ہے۔ اس شعور کی بیداری کا محرک انیسویں صدی کے اواخر کی ’’روحِ عصر‘‘ ہے،جسے حالی نے مقدور بھر جذب کیا تھا۔ یہ روح عصر’’تاریخیت‘‘ ہے؛یہ کہ ہر شے تاریخ کی پیداوار ہے،تاریخ ایک چاک ہے جس پر اشیا و مظاہر ڈھلتے اور وہی صوررتیں اختیار کرتے ہیں جو تاریخی قوتیں ’چاہتی‘ ہیں۔ سرسید کی آثار الصنادید،آئین اکبری(تدوین)،تاریخ سرکشی ِبجنور،خطبات احمدیہ، شبلی کی المامون،الفاروق، سوانح مولانا روم، ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان، شرر کی تاریخی ناول نگاری اور خود حالی کی حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید ’’تاریخیت‘‘ میں عقیدہ رکھنے کی عملی مثالیں ہیں۔ دوسری طرف انیسویں صدی کی مغربی فکر بھی تاریخ کو ہر شے کا مرکزی تنظیمی اصول گردانتی تھی۔ حیاتیات(ڈارون کا نظریہ ء ارتقا)، لسانیات یا فلالوجی(ولیم جونز،میکس مولر،فرانز بوپ)میں تاریخی مطالعات ہی کیے جاتے تھے۔ برعظیم کے نو آبادیاتی آقا بھی اپنے تمام نو آبادیاتی کلامیوں کی تشکیل میں تاریخ کو مرکز میں رکھتے۔
ہمیں حالی کے تصور قوم کی روح تک رسائی کے لیے، یہاں اس عہدکی یورپی لسانیات کے ایک عام اصول کو متوازی طور پر رکھنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ اس اصول کا قوم پرستی کے کلامیے سے کس قدر گہرا تعلق ہے،یہ آگے چل کر ازخود واضح ہو جائے گا۔
انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل کی یورپی لسانیات اشتقاق (Etymology)سے گہری دل چسپی رکھتی تھی۔ ۱۸۵۹ء میں ہینسلائی ویجووڈ نے انگریزی اشتقاقات پر اپنے لغت کی پہلی جلد شائع کی۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتا ہے کہ فن ِ اشتقاق سے ان کو بھی دل چسپی ہوتی ہے جو زبان کے مطالعے کے ماہر نہیں ہوتے۔ اشتقاق دراصل یہ جاننا ہے کہ کسی لفظ کا ماخذ کیا ہے،ہماری اپنی یا اس سے متعلق زبانوں میں اس کے ہم جنس الفاظ کی کیا شکلیں ہیں؟(۲۲)تمام اشتقاقی مطالعات دو تیقنات پر استوار ہوتے ہیں۔ قدیم ہی اصل ہے اور موجود،قدیم سے ماخوذ ہے۔ یعنی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر لفظ کی ایک قدیم اصل موجود ہے۔ لفظ کے موجودہ معانی خواہ جس قدر اپنی اصل سے مختلف نظر آئیں،وہ اپنی قدیم اصل سے آزاد نہیں ہوسکتے؛ان کا ہونااور موجودہ صورت میں ہونا ،قدیم کا مرہونِ منت ہے۔ لہٰذا لفظ کے موجودہ معانی کو سمجھنے کے لیے قدیم اصل سے رجوع لازم ہے۔
گذشتہ سطور میں حالی کے تاریخی شعور کی جس بیداری کا ذکر ہوا ہے،اس کی کارکردگی لفظ کے اشتقاقی مطالعات میں مضمر تیقنات سے غیر معمولی مطابقت رکھتی ہے۔ کیا ہم اسے اتفاق قرار دے سکتے ہیں کہ حالی نے ہندوستانیوں کے لیے ایک قوم کا تخیل پیش کرنے سے پہلے، ان کی شناخت الگ الگ مذہبی اور مسلکی گروہوں کے طور پر کی ہے؟حالی کی قومی شعری فکر میں جس اہم ترین لمحے کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو ا ہے،وہ اس الجھن سے عبارت ہے کہ جدا مذہبی شناخت رکھنے والوں کو کیا زمین ’’ایکا‘‘ دے سکتی ہے؟ یہ بات محض ایک سیاسی سوال سے زیادہ ایک ثقافتی الجھن اس لیے تھی کہ زمین کو قوم کی اساس قرار دینے کالازمی نتیجہ قوم کے تشکیلی عناصر میں مذہب کو زمین کے بعد درجہ دینا تھا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ مذہب کا انسانی زندگی میں کردار، اس کے زمینی رشتوں کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہوتا ہے، یہ امر بدیہی تھا کہ مذہبی شناخت واضح اور بیّن تھی،زمین کی شناخت ایک نیا تخیل تھی۔ کیا ایک واضح شناخت کو ایک نئی تخیلی شناخت کے تابع رکھا جا سکتا تھا؟یہیں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حالی نے ہندوستانیوں میں جس تفرقے کا ذکر کیا ہے،وہ مذہبی کیوں؟ لسانی،نسلی کیوں نہیں؟ کیا حالی نے یہ تسلیم کیا کہ ہندوستانیوں کی سب سے بڑی شناخت، مذہبی ہے؟اس سوال کا جواب ہم نفی میں نہیں دے سکتے ۔ ہندوستانیوں کی مذہبی شناخت پر اصرار ایک استعماری کلامیہ تھا۔ حالی نے اسے قبول کیا۔ گذشتہ صفحات میں مقدمے سے حالی کا ایک اقتباس نقل ہوا ہے، جس میں وہ یورپ اور ہندوستان /مشرق کا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ ’’وہ‘‘ قومی اور ’’ہم‘‘ مذہبی ہیں۔ یہ ٹھیک وہی تفریق پسند فکر ہے،جس کی نشان دہی انھی صفحات میں کی گئی ہے۔ بہ ہر کیف حالی قومی اور مذہبی شناخت کو ایک دوسرے کا مدمقابل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ قومی،مذہبی کے مقابلے میں ’’سیکولر‘‘ ہے۔ لہٰذا حالی مذہبی شناختوں کو ایک ’’سیکولر قومی‘‘ شناخت میں ضم کرنے کی سعی کرتے ہیں،مگر جلد ہی انھیں اپنی سعی میں الجھنوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔
اس الجھن سے نکلنے کی کوشش میں وہ روحِ عصر یعنی تاریخیت سے استمداد کرتے ہیں،اورٹھیک وہی طریق ِ کار استعمال کرتے ہیں،جو اس عہد میں فلالوجی میں ایک ’’اصل‘‘ کی تلاش میں بروے کار لایا جا رہا تھا۔ ہر لفظ کی طرح،ہر قوم کی بھی ایک ’’اصل‘‘ ہے،جو قدیم ہے اور قدیم ہی اصل ہے۔ لفظ کے موجودہ معانی میں جتنی گڑ بڑ،عدم تعین اور تنوع ہے،اس کا باعث یہ ہے کہ وہ لفظ اپنی قدیم ’’اصل‘‘ سے دور ہے۔ لہٰذا حالی کے لیے یہ سمجھنا ’فطری‘ تھا کہ ان کی الجھن کا حل بھی قدیم ’’اصل’’ تک رسائی میں ہے۔ اس رسائی کو ممکن تو تاریخیت نے بنایا،مگر اسے سہل اس عہد کی ایک خاص صورتِ حال نے بنایا۔ یہ صورتِ حال بھی لسانی تھی؛ہندی اردو تنازع۔
’حبّ وطن ‘ اور ’پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ‘ لکھنے کے بعد حالی ۱۸۸۸ء میں ’ترکیب بند موسوم بہ شکوہء ہند‘ لکھتے ہیں۔ یہ نظم نظر بہ ظاہرہندوستانی مسلمان کے سرزمینِ ہند کے نام ایک تخیلی خطاب پر مشتمل ہے؛نظم کا متکلم ہندوستانی مسلمان ہے، جو ہند کی سرزمین سے شکو ہ کناں ہے؛مگر اصل میں یہ قومی شناخت کی اس الجھن سے نکلنے کی ’’ تاریخی /لسانی‘‘کوشش ہے، جو ہمارے ’نئے شاعر ‘ کو قوم کا ’سیکولر‘ زمین اساس تصور قبول کرنے کی وجہ سے درپیش ہوئی تھی۔ اس نظم میں تخیلی متکلم اور تخیلی مخاطب دراصل قوم کے مذہبی تصوراورزمینی/وطنی تصورکے نمایندہ ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس نظم میں حالی نے مکالمے اور مناظرے کی وہ تیکنیک استعما ل نہیں کی، جو اس سلسلے کی پہلی نظموں میں ملتی ہے۔ اس نظم میں مکالمہ نہیں، خطاب ہے ؛ مذہبی تصور قومیت کا حامل تخیلی کردار محو تکلم ہے اور مخاطب خاموش ہے۔ دوسرے لفظوں میں قوم کے زمینی تصور کا نمایندہ خاموش ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نظم کے یہ اشعاردیکھیے:
جو نشاں اقبال مندی کے ہیں وہ سب ہم میں تھے
حبّ دینی ہم میں تھا قومی مؤدّت ہم میں تھی
تو نے دیکھا تھا کبھی اسلامیوں کا حال یہ
کیا عرب سے لے کے نکلے تھے یہی اسلام ہم
وہ مسلمانوں کی ہر بازی میں سبقت کیا ہوئی
وہ حجازی غیرت اور کلّی محبت کیا ہوئی
جب تک اے ہندوستاں ہندی نہ کہلاتے تھے ہم
کچھ ادائیں آپ میں سب سے جدا پاتے تھے ہم
تھے نہ کرگس اور زغن کی طرح ہم مردار خور
تھا وہی قُوت اپنا جو خود مار کر لاتے تھے ہم
حال اپنا سخت عبرت ناک تو نے کر دیا
آگ تھے اے ہندہم کوخاک تو نے کر دیا
تیرے سایہ سے رہے اے ہند جب تک دور ہم
اپنی یک رنگی رہی ضرب المثل بین الا مم
ملتِ بیضا نے قوموں کی مٹادی تھی تمیز
تھے بلال و جعفر و سلماں برابر محترم
کر دیے تو نے تمام اسلام کے ارکان سست
ہوگئے بودے ہمارے عہد اور پیمان سست
تھی ہماری دولت اے ہندوستاں فضل وہنر
آگیا تیری بدولت اپنی دولت کو زوال
ہم کو ہر جوہر سے یوں بالکل معرّا کر دیا
تو نے اے آب و ہواے ہند یہ کیا کر دیا(۲۳)
غور کیجیے :ان اشعار میں دو ہی باتیں واضح ہیں۔ ہماری ایک ’اصل‘ تھی ؛ایک اصلی جوہر تھا۔ آب و ہواے ہند نے ہمیں ان سے دور کردیا۔ ہم تب تک اپنی اصل یعنی عرب سے جڑے رہے جب تک ہم ہندی نہ کہلاتے تھے۔ ہند کے سائے سے جب تک دور رہے،ہماری یک رنگی(اور ایک اصل) اقوام عالم میں ضرب المثل تھی۔ ہند نے ہمیں آگ سے خاک کر دیا۔ گو یا حالی کے نئے قومی تصور میں اب سرزمینِ ہند ’غیر‘ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس’غیر‘ کا وہ کردار نہیں،جو ’تفرقے‘ کا تھا۔
یہ نظم نہ صرف حالی کی قومی شاعری میں بلکہ اردو کی قومی شاعری میں بھی ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم کے مرکزی خیال کی تعمیر ’’ہم‘‘ اور ’’وہ‘‘ کی تفریق کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ہرچند یہ تفریق اس نوع کی نہیں ہے جو ہمیں استعماری بیانیوں میں ملتی ہے اور جس کے ذریعے’’ہم‘‘ کو ’’وہ‘‘ پر مستقل اجارہ حاصل ہوتا ہے۔ بایں ہمہ حالی کے یہاں ’’ہم ‘‘ اور ’’وہ‘‘ میں ایک ایسا امتیازضرور ابھارا گیا ہے جو دونوں میں اشتراک و امتزاج کو محال بناتا محسوس ہوتا ہے۔ بیسویں صدی کی قومی اردو شاعری مذکورہ تفریق کے منطقی مضمرات کے انکشاف ہی سے عبارت ہے۔
حالی کی اس نظم میں واضح طور پر فلالوجی اور عتیقیا ت کی اس نو آبادیاتی آئیڈیالوجی کی کارفرمائی نظر آتی ہے، ’’جس کے مطابق کوئی متن جتنا قدیم ہو، وہ اتنا ہی خالص ہے اور جس قدر وہ نیا ہے،اسی قدر وہ ماخوذ اور دوغلا ہے۔‘‘(۲۴ )مسلمان قوم کا قدیم متن عرب ہے اور وہی خالص ہے،ہندی مسلمان اس اصل متن ہی سے ماخوذ ہے مگر ’نیا‘ ہونے اور اصل سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ’خالص‘ نہیں رہ گیا۔ حالی جب یہ کہتے ہیں کہ :ملت ِ بیضا نے قوموں کی مٹا دی تھی تمیز، تو وہ قوم اور ملت کے تصورات کے درمیان خطِ امتیاز کھینچ دیتے ہیں۔ یہاں حالی نے بہ ظاہر قوم کو اس کے مغربی مفہوم میں پیش نہیں کیا،مگر جن صحابہ کرامؓ کے ملتِ بیضا میں ضم ہونے کی مثال پیش کر رہے ہیں،ان کی قومی پہچان جغرافیائی ہے۔ حضرت بلال حبشی،جعفرطیارعربی اور حضرت سلمان فارسی۔ ان کی قومی اور جغرافیائی شناختیں، ’ایک اصل ‘سے جڑنے کے بعد محو ہو گئیں۔ ’شکوہ ء ہند ‘ میں اس امر پر اصرار صاف محسوس ہوتا ہے کہ ’آب و ہواے ہند‘ نے مسلمانوں کو جب ہر جوہر سے معرا کیا تو اس ’اصل‘ سے بھی دور کردیا اور وہ قومی اور جغرافیائی شناخت کے اسیر ہوگئے۔ مسلمانوں کی یہ شناخت بیسویں صدی میں ملت کے اس تصور میں اپنی پوری قوت سے ظاہر ہوئی جسے اقبال نے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی قومی اور ملی شاعری کی بنیادیں حالی ہی نے رکھیں۔ اقبال کے ’شکوہ‘ کا بیج بھی ہمیں ’شکوہء ہند‘ میں دکھائی دیتا ہے۔
شکوہء ہند کی قرأت حالی ہی کے ایک مقالے ’’تدبیر‘‘(مطبوعہ تہذیب الاخلاق، ۱۸۷۹ء)کے متوازی کریں تو اس نظم سے متعلق کچھ اہم نکات مزید واضح ہوتے ہیں۔ حالی مذکورہ مقالے کے آخری حصے میں ہنری ٹامس بکل(تاریخِ تمدن کے مصنف) کے اس نظریے کی روشنی میں بحث کرتے ہیں کہ نیچرل فنومنا انسانی تمدن پر اثر اندازہوتے ہیں۔ حالی، بکل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ’’ جن ملکوں میں نیچرل فنامنا یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور دہشت انگیز ہوتے ہیں وہاں خواہ مخواہ وہم غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔‘‘(۲۵ )حالی جس تفصیل سے بکل کے خیالات زیرِ بحث لاتے ہیں، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ انھیں بکل کے تمدنی نظریے میں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان قوم کیوں زوال کا شکار ہوئی؛حبّ دینی،قومی مودّت، حجازی غیرت اوراپنے فضل و ہنرکی دولت سے محروم کیوں ہوئی؟سیاسی زوال اور تمدنی زوال کیا ایک چیز ہے اوراگر الگ ہیں تو دونوں میں کیارشتہ ہے، حالی اس پر غور کیے بغیرزوال کی ذمہ داری نیچرل فنومنا یعنی ’’آب و ہواے ہند‘‘پر عائد کرتے ہیں جس نے مسلمانوں کو ہر جوہر سے معرا کردیا۔ چناں چہ کل کے ہندی مسلمان حکمران اورآج کے انگریزآقا دونوں بری الذمہ ہوگئے ! ذمہ داری کا بارِ گراں ایک ایسے’ عنصر‘پر ڈال دیا گیاجسے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ فطرت کی جبریت کا یہ تصورحالی کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوتا ہے جسے وہ سیاسی جبریت کی نشان دہی کے ’خطرناک’ عمل سے بچنے میں خوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہی خیال حالی نے اپنے قطعے’’ انگلستان کی آزادی اور ہندوستان کی غلامی‘‘ میں بھی دہرایا ہے:کہتے ہیں آزاد ہوجاتا ہے جب لیتا ہے سانس / یاں غلام آکر، کرامت ہے یہ انگلستان کی ۔۔۔۔۔۔ قلب ِ ماہیت میں انگلستان ہے گر کیمیا /کم نہیں کچھ قلبِ ماہیت میں ہندستان بھی۔۔۔۔آن کر آزاد یاں آزاد رہ سکتا نہیں /وہ رہے ہو کر غلام اس کی ہوا جن کو لگی
بکل سے پہلے بقراط، ارسطو، جاحظ اس نکتے پر اظہارِ خیال کر چکے تھے کہ مظاہر فطرت، انسانی فطرت پر اثرات مرتب کرتے ہیں اور ابنِ خلدون نے تو اسے ایک نظریے کی شکل دی کہ انتہائی گرم اور انتہائی سرد اقالیم اخلاقِ انسانی پر اور اس کے نتیجے میں انسانی تمدن پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کامل ترین تمدن صرف بلادِ معتدلہ میں پایا جاتا ہے۔ ’’ابنِ خلدون شام اور عراق کو اسی اقلیم[معتدلہ]میں شامل کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ شام یہودیت اور نصرانیت کا گہوارہ تھا اور گذشتہ زمانہ میں عراق میں اشوری تمدن سر سبز و شاداب ہوا۔۔۔۔لیکن ابنِ خلدون کو ایک مشکل پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ بلادِ عرب جو اسلام کا گہوارہ اور اس دولت مند اور لچک دار زبان کا وطن تھے جس نے دنیاے قدیم پر غلبہ حاصل کر لیا تھا،ان اقالیمِ معتدلہ میں شامل نہیں۔‘‘(۲۶) حقیقت یہ ہے کہ تمدنی ترقی و زوال میں مظاہر ِفطرت کو فیصلہ کن عنصر قرار دینے کا مطلب ان انسانی مساعی کی نفی ہے جو مظاہرِ قدرت پر غالب آنے کے سلسلے میں کی جاتیں اور جن کی وجہ سے انسانی تمدن کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بکل جن اچانک فطری حوادث پرواہمہ سازی کی ذمہ داری عائد کرتے ہیں،وہی حوادث دراصل انسان کے سامنے نئے سوال کھڑے کرتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں انسانی تخلیقی قوتیں بے دار ہوتی ہیں۔ تاہم تخلیقی قوت کی بے داری میں اس مجموعی تصورِ کائنات کا اہم کردار ہوتا ہے جس کا حامل کوئی انسانی معاشرہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جیسے فطری حوادث مختلف معاشروں میں مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر مسلمان اپنے حجازی جوہر سے محروم ہوئے تو اس کا باعث ’آب و ہواے ہند‘ نہیں،ہند کاتصورِ کائنات ہو سکتا ہے جسے ’’ہم‘‘ نے اختیار کر لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ’’مدو جزر ِ اسلام‘‘ میں حالی ایک نئے تمدن کی تخلیق میں مظاہرِ قدرت کے فیصلہ کن کردار کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں۔ مثلاً یہ بند دیکھیے:
نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور
کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر
نہ کچھ ایسے سامان تھے واں میسر
کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر
نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی
فقط آبِ باراں پہ تھی زندگانی(۲۷)
اگرچہ یہاں حالی یہ باور کراتے ہیں کہ اسلامی تمدن کی بنیادوحی پر ہے یعنی اس انسانی دنیامیں ’’غیرتِ حق کے حرکت میں ‘‘آنے پرجو بہائم سے بدتر ہوگئی تھی۔
حالی’ شکوہء ہند‘ میں مسلمان قوم یا ملت کے جس تصور کی نقش گری کرتے نظر آتے ہیں،اس میں ثقافت کے حرکی تصور کی گنجائش موجود ہی نہیں۔ وہ عرب مسلم ثقافت کی طرف تو کہیں نہ کہیں اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں،جیسے مسلمان کرگس اور زغن نہیں تھے؛شاہین تھے؛محنت پسند،باعمل،علم و فضل کے حامل تھے،مگر ہندوستان آتے ہی اس ساری ثقافتی میراث سے بیگانہ ہوگئے۔ اس طرف دھیان جاتا ہے کہ شاید حالی ’آب و ہواے ہند‘ کو مجاز مرسل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، اس سے مراد وہ تمام لوگ لے رہے ہیں جو ہندوستان میں آئے،غارت گری کی،یہاں حاکم ہوئے اور جنھوں نے مسلمانوں سے ان کا اقتدار چھینا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حالی کے لیے براہ راست انگریزوں کو مخاطب کرنا ممکن نہیں تھا،اس لیے انھوں نے ’آب و ہواے ہند‘ کے پردے میں وہ سب کہنے کی کوشش کی۔ اس بات کو ایک موہوم امکان کے طور پر پیشِ نظر رکھنے میں کوئی حرج نہیں،مگر اس کے باوجود نظم کا وہ تصور ملت پوری طرح برقرار و مستحکم رہتا ہے،جس میں ثقافتی حرکیت کی گنجائش نہیں۔ حرکی ثقافت ہی، ثقافتی آمیزش کو ممکن بناتی ہے۔ اس کا باعث، مولانا حالی کا ثقافتی تعصب نہیں۔ اس کا سبب ایک طرف وہ طریقِ کار ہے،جس کی مدد سے وہ ملتِ بیضا کی ’اصل‘ تک رسائی کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی ملی شناخت کو لاحق اس خوف کے سد باب کی خواہش تھی جو انیسویں صدی کے اواخر کی سیاسی اور ثقافتی صورتِ حال نے پیدا کیا تھا۔
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ برعظیم کے تمام قومی بیانیوں میں ’’اصل‘‘ کی تلاش دکھائی دیتی ہے اوراہم بات یہ ہے کہ ہر جگہ یہ اصل’ مذہبی‘ہے۔ ہندو قوم پرستی بھی اپنی اصل میں مذہبی تھی۔ بپن چندر پال نے ۱۹۱۰ء میں ’ہندوستانی قومیت پرستی کی روح‘ کے نام سے انگریزی میں ایک کتاب لکھی۔ اس میں ہندوستانی قوم پرستی (جو ہندو قوم پرستی ہی ہے)کی روح اور ’اصل‘ سے متعلق انتہائی بنیادی باتیں پیش ہوئی ہیں۔ بنگالی ہندوؤں نے قوم پرستی کی سیاسی تحریک شروع کی تھی اور انھوں نے ہی ابتدا میں اس تحریک کی روح واضح کی۔ چندرپال’ بندے ماترم ‘کو قوم پرستی کی تحریک کا نقطہء آغاز قرار دیتے ہیں اور اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ برعظیم میں قوم اور قومیت پسندی کے بیانیے شعری تخیل کی پیداوار ہیں۔ ان کے نزدیک اس نظم نے قوم پرستی کی تحریک میں مذہبی روح پھونک دی،جس سے انڈین نیشنل کانگریس محروم تھی۔ وہ کانگریس کے سیکولر کردار پر کھلے لفظوں میں تنقید کرتے ہیں۔ گویاقوم پرستی کا بیانیہ مذہبی اصل سے جڑے بغیر روح سے خالی ہوتا ہے۔ انھوں نے بندے ماترم کی جو تعبیر کی ہے،وہ قوم پرستی کی اس جہت کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد دیتی ہے،جس نے برصغیر کی سیاسی اور ثقافتی تقدیر کا فیصلہ کیا۔
فلالوجی اور قومی بیانیوں میں ’اصل‘تک رسائی کا عمل آرکیالوجی کی تحقیق نہیں تھا،جس میں کسی پرانی شے کواس کی اصل صورت میں ملبے کے انبار سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں ’اصل‘ ایک تشکیل تھا۔ اس کی مثال میں ’بندے ماترم’ کی ’اصل‘ سے متعلق بپن چندرپال کی یہ توضیحات پیش کی جاسکتی ہیں:
’’بندے ماترم‘‘ حقیقت میں ’’مادرِ وطن کو سلام‘‘ نہیں بلکہ ’’ماں کو سلام‘‘ ہے۔ یہ ’’ماں‘‘ جس کا اطلاق الوہیت پر ہوتا ہے،ہندومت میں ایک قدیمی لفظ اور قدیمی تصور ہے،جو خدامیں نہ صرف پدریت کا بلکہ مادریت کا بھی اثبات کرتا ہے۔ ’’باپ‘‘ کی اصطلاح الوہیت سے متعلق ہوکر، اس کی قدرتِ محافظت کی علامت بن جاتی ہے؛’’ماں‘‘ کا لفظ خاص طور پر اس کی قوتِ تخلیق کی علامت ہے۔ ان سب دیویوں کی یہ مشترک خصوصیت ہے،جنھیں ہندو پوجتے ہیں،مثلاً کالی،درگا،لکشمی،سرسوتی۔۔۔۔ان سب کو ہمیشہ ’’ماں‘‘ کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ ’’بندے ماترم ‘‘ میں اس’’ماں ‘ ‘نے ان سب [دیویوں] کو ایک نئی ترکیب میں ضم کیا ہے اور قدیمی،مقدس،انتہائی محبوب اصطلاح، مادرِ وطن کے ایک نئے تصور کے لیے استعمال کی ہے۔ اس پرنام کے ذریعے ملک میں ایک نیا عقیدہ یعنی حبّ الوطنی کا عقیدہ وجود میں آیا ہے۔‘‘(۲۸)
اگرچہ چندرپال نے یہ واضح کرنا ضروری خیال کیا ہے کہ ’بندے ماترم‘کسی کے خلاف نہیں،بلکہ یہ عالم گیرانسانیت سے متعلق ہے۔ گویا ہندو قوم پرستی کی اس اہم ترین مثال میں ’غیر‘کی موجودگی سے انکار کیا ہے۔ حال آنکہ بنکم چندر چٹر جی نے اسے اپنے ناول کے سلسلے میں لکھا جو بنگال میں مسلم اقتدار کے خلاف جدوجہد سے متعلق تھا اور اس میں ایک بند بھی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ نیز چندرپال جب اس ترانے کو عالم گیر انسانیت سے بھی متعلق قرار دیتے ہیں تو مہا وشنو اور نارائن کی مثال لاتے ہیں۔ کیا ایک مذہبی گروہ کا نمایندہ کردار(اس کا حقیقی یا اساطیری ہونا، اس کے ماننے والوں کے لیے یکساں ہوتا ہے)سب مذاہب کے لیے قابلِ قبول ہو سکتا ہے،خاص طور پر اس صورت میں جب اس کردار سے وابستہ خصوصیت،دوسرے مذاہب کے کرداروں میں بھی موجود ہو اور یہ بات عقیدے کا معاملہ ہو؟یہاں مسئلہ مماثلت سے زیادہ، مسابقت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مذہبی مسابقت سے زیادہ شدید مسابقت کوئی اور نہیں۔
قومی شاعری میں ’اصل‘ کے مذہبی تصور کو اگر ہم خالص ہیئتی سطح پر دیکھیں،یعنی اسے ایک شعری مسئلے کے طور پر لیں،تو ایک دل چسپ صورتِ حال سامنے آتی ہے۔ قومی شاعری کا وہ حصہ جس میں زمین اور جغرافیے کو قوم کی اساس سمجھا گیا ہے،وہ مناظر فطرت کی مصوری پر مبنی یا اخلاقی نوعیت کاایک کلام ِ موزوں ہے،مگر جس قومی شاعری میں مذہب کی قدیم اور اصلی (جنھیں ہم معنی سمجھا جاتا ہے)صورت کو ملت کی بنیاد تصور کیا گیا ہے،اس شاعری میں ایک نئی شعر ی حسیت نے جنم لیا ہے۔ حالی کی مسدس کے وہ حصے بہ طور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں اسلام کے ابتدائی عہد کا نقشہ دل گداز پیرائے میں کھینچا گیا ہے۔
قدیم، مقدس اصل کی جستجو، پرومیتھیس کی طرح (اپنی ملت کے) انسانوں کے لیے آگ لانے سے عبارت تھی۔ حالی نے یوں ہی نہیں کہا کہ :آگ تھے اے ہندہم کوخاک تو نے کر دیا۔ آگ ’اصل‘ ہے۔ آگے اردوشاعری میں آگ اور اس کے تلازمات کسی نہ کسی شکل میں اسی ’اصل‘ سے جڑے ہیں۔ یہ بھی اتفاق نہیں کہ زمانہء حال کی ہر نوع کی تاریکی دور کرنے کے لیے اس ’اصل‘ کی آگ سے حرارت اور نور حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قدیم اصل کی جستجو اجتماعی سائیکی کے ان منطقوں میں اترنے سے عبارت تھی،جہاں کتنے ہی کردار، تجربات،کیفیات مثالیوں کے طور پر مضمر تھے۔ اقبال اور راشد کے یہاں آتش و نور کے تلازمات کا سیاق ’اصل‘اور کھوئے ہوؤں کی جستجو ہے۔ تاہم اس شاعری کا سارا گداز، اجتماعی وجود کے بنجر پن کے شدید احساس کے مقابل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر اپنے خاک اور راکھ ہونے کا کرب ناک احساس ہوتا ہے،اسی قدر’اصل ‘اور قدیم کی آگ دلوں میں الاؤ سا روشن کرتی ہے۔
٭
قومی شاعری میں اگر ہم ’اصل‘ کی تلاش کو ایک ناگزیر تاریخی ضرورت قرار دیں،تو پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اصل کی تلاش میں کیامذہب ہی واحد منزل تھی؟اس سوال پر بحث اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ تسلیم کرتے ہوں کہ تاریخ اور تاریخی ضرورتیں، انسانی ارادوں، مقاصد،عزائم سے پیدا ہوتی ہیں۔ تاریخ،انسانی مساعی اور ان کی کش مکش کا نتیجہ ہے۔ یہ تصورِتاریخ، تاریخ میں الوہی مداخلت کا امکان تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذاس تصور کی رو سے، تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے،اس کے اسباب ان انسانی مقاصدمیں تلاش کرنے چاہییں جو عمل کے بعض امکانات کو جنم دیتے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیں تو قومی شناخت کے لیے ’اصل‘ دریافت کرنا ہی واحد امکان نہیں تھا،تاہم یہ بات بھی اتنی ہی درست ہے کہ یہی امکان فوری دست یاب اور سہل تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے قومی شناخت کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب وہ نہ صرف محکوم تھے بلکہ نو آبادیاتی حاکموں کی ’تہذیب آموزاصلاحات‘ کی زد پر بھی تھے۔ سیاسی بے اختیاری اور ثقافتی عدم استحکام دونوں تھے۔ چناں چہ وہ اپنی شناخت کے لیے آگے سے زیادہ پیچھے دیکھنے پر مجبور تھے۔ وہ مستقبل کے خوابوں اور آدرشوں سے اپنی قومی شناخت کے خدوخال واضح کرنے کے بجائے، ماضی کی آگ سے اپنے قومی تخیل کو روشن کرنے پر مجبور تھے۔ مگر کیا ماضی کا دوسرا نام مذہب تھا؟کیا ہندوؤں اور مسلمانوں کے ماضی میں واحد محفوظ لنگر مذہب ہی تھا،جس کی طرف وہ اپنی قومی شناخت کی ڈولتی کشتی لے جا سکتے تھے؟یہ سوال اس وقت اور بھی اہم ہو جاتاہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کے اقتدار کے زمانے میں دونوں کی مذہبی شناختوں نے خودکو ایک سنگین مسئلے کے طور پر کبھی پیش نہیں کیا تھا۔
اس سوال کا جواب ہمیں اس تفریقی فکر میں ملتا ہے،جو انیسویں صدی کے نوآبادیاتی برعظیم میں حاوی فکر تھی۔ انگریزاستعمار کاروں نے یورپی اور ایشیائی تہذیبوں میں سب سے بڑی جس تفریق کا چرچا کیا تھاوہ عقل اور مذہب کی تفریق تھی۔ یورپی تہذیب کی سب سے بڑی قوت عقل اور ایشیا/ مشرق کی تہذیبی اساس مذہب ہے۔ یہاں ایڈورڈ سعید کے لفظوں میںStrategic Formation سے کام لیا گیا ہے،جس کے ذریعے یورپ، مشرق پر اپنی اقتداری حیثیت کو ہمہ گیریت دیتا ہے۔(۲۹ ) دوسرے لفظوں میں مشرق ہو یا مغرب،دونوں انسانی ثقافتی حقیقتیں ہیں۔ دونوں میں وہ سب صلاحیتیں اور سرگرمیاں ، درجے کے فرق کے ساتھ اور تاریخی ارتقا کے فرق کے ساتھ موجود ہیں،جن سے انسانی ثقافتیں وجود میں آتی ہیں۔ مغرب کی ثقافت میں بھی مذہب کا عمل دخل رہا ہے اور مشرق کی تاریخ بھی عقلی سرگرمیوں سے خالی نہیں ہے۔ سائنس، لسانی مطالعات اور فلسفے میں عرب مسلمانوں اور ہندوؤں کی خدمات عالمی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر مذہبی شدت پسندی یورپ میں رہی ہے،دنیا کے شاید ہی کسی خطے میں رہی ہو۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے جھگڑوں میں خونریزی کی ناقابلِ یقین مثالیں سامنے آئیں۔
اہم بات یہ ہے کہ حالی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ’’ہم‘‘ اور ’’وہ‘‘ میں قومی اور مذہبی احساس کا فرق ہے اور یہ فرق شاعری میں بھی نظرآتا ہے ؛یا ایشیائی اور یورپی شاعری میں یہ فرق ہے کہ ’’یورپ کی شاعری درحقیقت نیچر کی ترجمانی ہے۔ اس کا میدان اسی قدر وسیع ہے جس قدر نیچر کی فضا‘‘(۳۰) جب کہ اردو شاعری نیچر سے دور اور خیالی ہے۔ لہٰذ وہ مغرب کی عقلیت پسندی کی اس خصوصیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں جومشرق کی مذہبیت پسندی کے مقابلے میں خود کو نمایاں کرتی ہے۔ حالی جب پرانے رنگ کو ترک کرتے ہیں تو گویا شاعری میں مشرق کی مذہب پسندی (بہ حوالہ انیس و دبیر)کو ترک کر کے قومی اور نیچرل شاعری اختیار کرتے ہیں۔ انجمنِ پنجاب کے تحت لکھی گئی ان کی قومی نظمیں مغرب کی ’’سیکولر قوم پسندی‘‘سے عبارت نظمیں ہیں۔ یہ قوم پسندی بھی ایک اخلاقی جہت رکھتی ہے،مگر جب حالی قومی شناخت کے مسئلے سے داخلی سطح پر دوچار ہوتے ہیں تو وہ جس ’اصل‘کا تخیل باندھتے ہیں،وہ بھی ایک مغربی تشکیل ہے: مشرق کی شناخت اور اساس مذہب ہے۔
قصہ یہ ہے کہ حالی کی قومی شاعری، قوم سے متعلق مغربی تشکیلات سے انحراف نہیں کرتی۔ حالی کا تصورِ قوم،جوں ہی ’’عوامی منطقے‘‘سے مس ہوتا ہے اس میں یورپی تخیلاتِ قوم برق بن کر دوڑنے لگتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی قومی شاعری میں مغرب کسی بھی رنگ میں ’’غیر‘‘ کے طور پر سامنے نہیں آتا؛ان مقامات پر بھی نہیں جہاں ہندوستانی مسلمانوں کی تباہ حالی میں یورپی استعماریت کا ذکر ناگزیر ہوتا ہے۔ حالی کے لیے مغرب شائستگی،تعلیم،آزادی،ترقی سے عبارت ہے۔ یہی عناصر وہ اپنی قوم میں دیکھنا چاہتے ہیں:
سب سے آخر کو لے گئی بازی
ایک شائستہ قوم مغرب کی
یہ بھی تم پر خدا کا تھا انعام
کہ پڑا تم کو ایسی قوم سے کام(۳۱)
حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں
ترقی کی راہیں سراسرکھلی ہیں
صدائیں یہ ہر سمت سے آرہی ہیں
کہ راجا سے پرجا تلک سب سکھی ہیں
تسلط ہے ملکوں میں امن و اماں کا
نہیں بند رستہ کسی کارواں کا(۳۲)
مشرق کے ماضی میں مذہب کے علاوہ شناختیں موجود تھیں ؛سائنس، فلسفہ،، فنِ تعمیر، مصوری، شاعری،خطاطی۔ ان کا ذکر ضرور ہوتا رہا،ان پر تفاخر کا اظہار بھی ہوتا رہامگر انھیں اپنے ملی تصور میں گوندھنے کی کوشش عام طور پر نہیں ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ مذکورہ شناختیں تاریخی طور پر مذہب سے متصادم نہیں تھیں،مگر انیسویں صدی کے مسلم قوم پرستی کے تصور میں انھیں خارج رکھا گیا۔ یہی نہیں،ان میں سے بعض پر تو باقاعدہ شرمندگی محسوس کی جانے لگی۔ اس کی بڑی مثال شاعری ہے۔ حالی نے ’مدو جزر اسلام ‘میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے اور ایک شعر تو یکسر اپنے عمومی میلان سے ہٹ کر کہا ہے:
لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے
بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے(۳۳)
حالی کا یہاں اشارہ ابن رشد کی طرف محسوس ہوتا ہے جنھوں نے مغربی مفکرین سے کہیں پہلے مذہب اور فلسفے میں علمیاتی امتیاز قائم کیا، تاہم دونوں کو حقیقت تک رسائی کے ذرائع قرار دیا۔ فلسفے کو حقیقت تک رسائی کا ذریعہ تسلیم کرنا، دراصل الوہی فکر کے ساتھ ساتھ انسانی فکرکی اصالت میں یقین پیدا کرنا تھا اور یہی لبرل ازم تھا۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ یہ لبرٹی،لبرل ازم اور ان سے پیدا ہونے والے علوم اور روّیے مسلم قوم پرستی کا حصہ نہیں بنتے۔ حالی اور ان کے بعد کے لوگ حتیٰ کہ اقبال تک استقرائی فکر میں مسلمانوں کی اوّلیت کا چرچا کرتے ہیں مگر جب مسلم قوم کی شناخت واضح کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو لبرل ازم کو خارج رکھا جاتا ہے اور اسے ایک مغربی مظہر قراردے دیا جاتاہے۔ اس کی سیدھی سادی وجہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی شناخت ’اصل‘ یعنی عرب کے چشمہ ء صفا تک محدود ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی شناخت کو تاریخ کے متحرک دھارے کی بجائے ’واحد،مستند،کلاسیکی متن‘ سے وابستہ کرنے کا عمل ہے۔ قصہ مختصر ہم حالی کے تصور قوم کو ’قدیم عرب ‘ اور ’جدید مغرب‘ کا امتزاج قرار دے سکتے ہیں۔ قدیم عرب، دین کی اور جدید مغرب، دنیا کی علامتیں ہیں۔ حالی کا یہ شعر: جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت / اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے، اسی تصور کی ترجمانی کرتا ہے۔ تاہم ایک توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ حالی کے قومی تخیل میں ماضی ایک پر شکوہ،عظیم،فائق یا د کے طور پر آتا ہے،ایک آگ سی ان کے دل اور شعری جمالیات میں لگا جاتا ہے، جب کہ حال ایک محدود، فوری عمل پر اکسانے والی حقیقت کے طور پر۔ دوسرے لفظوں میں وہ دین کی اصل کا جس قدر بلند اور ارفع تصور کرتے ہیں، دنیا کا اسی قدر محدود تصور کرتے ہیں۔ وہ عرب کی یاد سے جو ایک آتش و نور کی سوغات اپنی شاعری میں لاتے ہیں،اس سے وہ جدیدمغرب سے عبارت دنیاکو روشن نہیں کرتے۔ عرب اور مغرب میں ایک فاصلہ، ان کی قومی شاعری اور ان کے تصور قوم میں برقرار رہتا ہے۔ ان کے لیے دنیا: جدید،مغرب، نوکری، تعلیم،تجارت سے عبارت ہے۔ نیز وہ سر سید کے زیر اثر مغرب یا یورپ کو جس شائستگی کی علامت قرار دیتے تھے اور اسے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ناگزیر ٹھہراتے تھے،وہ انھیں عرب کی آگ سے جدید دنیا کو روشن کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ان کا تصور قوم وفادار، فرماں بردار شہری تک محدود تھا۔ عرب کی یاد سے جو آگ ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی، اس میں بغاوت،مزاحمت کی اتنی ہی صلاحیت تھی،جس کا مظاہرہ ہندو نیشنلزم میں ہوتا تھا اور جس پر سرسید شدید معترض ہوتے تھے۔ اس آگ کو پابند کرنے کا نتیجہ،سیاسی طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا نہ ان کی شاعری کے حق میں۔ حالی کی شاعر ی نے مسلمانوں کو اپنا تصورسیاسی وجود کے طور پر نہیں،نوکری پیشہ دنیادار کے طور پر کرنے کی ترغیب دی اور خود یہ شاعری،ایک خشک تبلیغی موزوں پیرائے میں سکڑ کر رہ گئی۔ حالی کے قومی تصور کی بھاری قیمت ان کی شاعری نے ادا کی۔
اس مقام پریہ سوال معرضِ بحث میں لانا ضروری ہے کہ کیاحالی کی قومی شاعری میں قومی بنیادوں پراستعماری غلبے کی نو بہ نو صورتوں کے خلاف مزاحمت کی گنجائش موجود تھی ؟دیوان کے دیباچے کے آغاز میں حالی نے جو شعر درج کیا ہے،وہ اس سوال پر بحث کا نقطہء آغاز بن سکتا ہے:
کچھ کذب و افترا ہے کچھ کذبِ حق نما ہے
یہ ہے بضاعت اپنی اور یہ ہے دفتر اپنا
یہ شعر چیخ چیخ کر کَہ رہا ہے کہ کوئی مصیبت تو حالی پر ایسی آن پڑی تھی کہ انھیں اپنی بضاعت اوراپنے دفتر شاعری کو کذب و افترا اور کذبِ حق نما کہناپڑا۔ یہ مصیبت دو طرف سے تھی:حالی کے معاصرین کی طرف سے اور خود ان کے اندر کی طرف سے۔ باہرکی طرف سے توحالی پر تابڑ توڑ حملے ہوئے اورمخالفین اعلان کرنے لگے کہ حالی کا حال میدانِ پانی پت کی طرح پائمال ہے،دوسری طرف خود حالی کے اندربھی کہیں گہری سطح پر کھد بد تھی،جو اکثر سرزنش کی صورت اختیار کرجاتی تھی اور حالی نے اس دوطرفہ مصیبت کے مقابلے کی خاطر’’شاعری‘‘ کی ’’اپالوجی‘‘ تیار کی۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ’’اپالوجی‘‘مقدمے میں ظاہر ہونے والے تصوراتِ شاعری سے کئی مقامات پر متصادم ہے، اور اس کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں کہ مقدمے میں ظاہر ہونے والے ارشادات تو اوروں کے لیے ہیں اور دیوان کا دیباچہ خود اپنے دفاع میں ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حالی یہ دفاع خود اپنے حضور بھی کرتے محسوس ہوتے ہیں۔
حالی پر باہر اور اندر سے ہونے والی تنقید کا ہدف ان کی قومی اور اصلاحی شاعری تھی۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس ساری تنقید کا بیج خود حالی کے تصورات اور ان کے تحت کی جانے والی شاعری ہی میں موجود تھا۔ وہ غور وفکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ [قومی] شاعری تخیل پر قوتِ ممیزہ کی حکم رانی کے بغیر ممکن نہیں۔ ’’شاعری‘‘ میں تخیل کے بے اعتدال ہونے کا اندیشہ برابر لاحق رہتا ہے۔ اگر شعری تخیل مبالغے اور بے اعتدالی سے بچ جائے تو قومی شاعری ممکن ہے۔ گویارخشِ تخیل کا میلان بے مہارآزادی کی طرف ہوتا ہے اور قوتِ ممیزہ، تخیل کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ حالی جسے قوتِ ممیزہ کہتے ہیں، وہ قوم کے تصورات اور مقاصد سے متعلق ’’عوامی منطقہ‘‘ ہے۔ تخیل اگر، خداداد ہے اور اس کا تعلق اندر سے ہے،ایک نجی منطقہ ہے تو قوتِ ممیزہ نہ صرف ’قومی و عوامی‘ہے بلکہ یہ عقلی و منطقی بھی ہے اور اس کا اظہار فلسفے اور تاریخ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا تخیل کی بنیاد پرسر زد ہونے والی شاعری میں آمد ہے،بے ساختگی ہے،ایک طرح کی بے ربطی ہے تو قوتِ ممیزہ کے تحت کی جانے والی شاعری میں آورد ہے،مقصدیت کی ساختگی اور جامعیت ہے۔ علاوہ ازیں جب تخیل پر قوتِ ممیزہ نگران ہوتی ہے تو شاعر کا نجی منطقہ،عوامی منطقے کے لیے جگہ خالی کرتا ہے۔ شاعر کی ذات میں رونما ہونے والا یہ عمل، سماجی سطح پر انجام دیے جانے والے اس عمل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں جہاں ’’ہم‘‘ کی ’’وہ‘‘ پر اجارہ داری قائم ہوتی ہے اور جس میں ’’وہ‘‘ وقتی طور پر پسپا ہوتا ہے مگر کسی نہ کسی شکل میں اور کہیں نہ کہیں ’’ہم‘‘ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مزاحمت کا رخ ’’ہم‘‘ ہی کے ہاتھوں متعین ہوتا ہے۔
ان معروضات کی روشنی میں حالی کی ’’اپالوجی‘‘ میں ظاہر ہونے والے یہ خیالات دیکھیے:
فلسفی یا مورخ ہر ایک چیز پر اس کے تمام پہلو دیکھ کرایک مستقل رائے قائم کرتا ہے اور اس لیے ضرور ہے کہ اس کا بیان جامع، مانع ہو، لیکن شاعر کا کام یہ نہیں ہے بلکہ اس کاکام یہ ہے ہر ایک شے کا جو پہلو اس کے سامنے ہو اور اس سے کوئی خاص کیفیت پیدا ہو کر اس کے دل کو بے چین کرے اس کو اسی طرح بیان کرے۔ پھر جب دوسرا پہلو دیکھ کر دوسری کیفیت پیدا ہو جو پہلی کیفیت کے خلاف ہو، اس کو دوسری کیفیت کے موافق بیان کرے۔(۳۴)
یہاں حالی فلسفہ،تاریخ اور شاعری میں فرق کرتے ہیں۔ یہ بات قطعی واضح ہے کہ فلسفی یا مورخ، قوتِ ممیزہ سے کام لیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ ایک مستقل رائے قائم کرتے ہیں۔ جب کہ شاعر متخیلہ کے تحت شعر تخلیق کرتا ہے،اس لیے اپنی کیفیات کے فرق پر دھیان نہیں دیتا۔ یہاں حالی ان دونوں کے اس بنیادی امتیاز پر اصرار کرتے ہیں،جسے اپنے مقدمے میں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں وہ شاعر کے نجی منطقے اور عوامی منطقے اور منطق میں جوڑ بٹھانے کی سعی پر سوالیہ نشان ثبت کرتے نظر آتے ہیں۔ الٹا ان دونوں کے بیچ ایک ایسے فاصلے کی موجودگی باور کراتے نظر آتے ہیں جس سے دونوں کی جداشناختیں قائم ہوتی ہیں۔ شاعری کی یہ شناخت، قومی شاعری کا امکان معدوم کرتی ہے۔ قومی شاعری، قوتِ ممیزہ کے عوامی منطقے کے بغیر ممکن نہیں؛قومی شاعری میں موضوع کا تسلسل،ایک گونہ جامعیت اور قوم کا کئی پہلوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ اگر شاعری میں قوم کی نسبت سے کبھی ایک بات اور کبھی اس کے برعکس بات ہو تو وہ شاعری قومی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شاعر ، اپنے تخیل کو آزاد اور بے اعتدال ہونے دے، اپنے نجی منطقے کو اس کے تلوّن کے ساتھ ظاہر ہونے کی اجازت دے دے اور اس کے نتیجے میں غیر معمولی تاثر آفریں اشعار تخلیق کرنے میں بھی کام یاب ہو جائے،وہ اہم شاعر ہو سکتا ہے،قومی شاعر نہیں۔ اگر ہم حالی کے اس موقف کو تسلیم کر لیں تو حالی کا قومی شاعری کا سارا سرمایہ معرضِ سوال میں آجاتاہے۔
شاعر ی اور فلسفے کا فرق ارسطو سے چلا آرہا ہے۔ ارسطو نے شاعری کو فلسفے کے مقابلے میں ان ناممکنات سے عبارت قرار دیا تھا جن کا ممکن ہونا، خارج امکان نہیں ہوتا۔ حالی دونوں کا فرق، ایک فلسفیانہ بحث کی روشنی میں نمایاں کرتے ہیں،مگر جلد ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ یہ سب ان تضادات کا جواب دینے کی خاطر کررہے ہیں جن کے بارے میں معین احسن جذبی نے لکھا ہے کہ ’’ حالی کے مطالعے میں جو چیز الجھن میں ڈالتی ہے وہ انگریزی حکومت کے بارے میں ان کے متضاد خیالات ہیں۔ وہ کبھی اس کی مدح سرائی میں مشغول نظر آتے ہیں،کبھی مذمت میں۔‘‘(۳۵) حالی کو بھی اپنے ان تضادات کا علم ہے۔ چناں چہ وہ اپنی ’’اپالوجی‘‘ کی بحث بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ’’ پس ممکن ہے کہ شاعر ایک ہی چیز کی کبھی تعریف کر ے اور کبھی مذمت اور ممکن ہے کہ وہ ایک اچھی چیز کی مذمت کرے اور بری چیز کی تعریف، کیوں کہ خیرِ محض کے سوا ہر خیر میں شر کا پہلو اور شرِمحض کے سوا ہرشر میں خیر کا پہلو موجود ہے۔‘‘(۳۶) اپنی بحث کو خالص علمی سطح پر استوارکرنے کا تاثر دینے کے بعد جلد ہی بر سر مطلب آتے ہیں ـ’’ وہ [شاعر ] کبھی ایک ہی گورنمنٹ کی اس کی خوبیوں کے سبب سے ستائش کرتا ہے اور کبھی اس کی ناگوار کارروائیوں کے سبب شکایت،مگروہ کبھی ان حیثیتوں کی تصریح نہیں کرتاجن پر اس کے مختلف بیانات مبنی ہوتے ہیں۔‘‘(۳۷)یہ الگ بات ہے کہ مطلب کی بات تک آتے ہوئے حالی،اپنی پہلی دلیل سے گریز اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ کبھی شاعر ایک ہی گورنمنٹ کی اس کی خوبیوں کے باوجود شکایت بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف حالی کے یہاں ایک عجب اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دفاع میں لکھتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہ طور شاعر یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی شاعری میں موجود تضادات کی تصریح کریں۔
دل چسپ بات یہ ہے کہ حالی اپنی قومی شاعری کے دفاع میں جس موقف کا اظہار کرتے ہیں،وہ ان کی اس کش مکش کا اظہار بن کر رہ جاتا ہے جوشاعری اور قومی شاعری کے سلسلے میں ان کے یہاں پیدا ہوگئی تھی۔ تاہم اس کش مکش سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ حالی کے دل میں اس شاعری کا کانٹا برابرچبھن پیدا کرتا رہا جسے وہ پسپا کر کے قومی و اصلاحی شاعری کر رہے تھے۔ اس تناظر میں دیکھیں توحالی کا اپنے دفتر شاعری کوکذبِ حق نما کہنا سمجھ میں آتا ہے اور حالی کی یہ بات بھی قابلِ فہم محسوس ہوتی ہے کہ ’’ خیرِ محض کے سوا ہر خیر میں شر کا پہلو اور شرِ محض کے سوا ہر شر میں خیر کا پہلو موجود ہے۔ ‘‘ حالی کی یہ دونوں باتیں اس تضاد کو حل کرنے کی کوشش نظر آتی ہیں جو شاعری اور قومی شاعری کے سلسلے میں ان کے یہاں موجود تھا۔ حالی یہ باور کرانے کی سعی کرتے ہیں کہ شاعری کذب ہے،مگر ایک ایسا کذب جو حق کی طرف راہ نمائی کر سکتا ہے۔ یا ایک ایسا شر ہے جس میں خیر کا پہلو موجود ہے۔ کیا حالی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی انگریزی گورنمنٹ کی تعریف ایک ایسا کذب ہے جس میں قوم کی راہ نمائی کی صلاحیت ہے؟یا ان کا مدعا یہ ہے کہ استعمار کے شر میں خیر کے پہلو موجود ہیں؟اور یہی وہ تصور ہے جو حالی کی قومی شاعری میں مزاحمت کے امکان کی راہ بند کرتا ہے۔ اس تصور کی رو سے فقط شرِ محض کے خلاف مزاحمت کی جا سکتی ہے اورجس شر میں خیر موجود ہو،اس کے خلاف مزاحمت چہ معنی؟
حالی بلاشبہ انگریز استعمار کی چالوں کا علم رکھتے تھے،یعنی اس کے شر ہونے سے آگاہ تھے، جس کا اظہار انھوں نے مسٹر اسٹیوک کی دربارِ قیصری منعقدہ ۱۸۷۸ء کے موقع پر لکھی گئی انگریزی نظم کے ترجمے بہ عنوان ’’زمزمہ قیصری‘‘ کے حواشی میں تفصیل سے اور اپنے بعض اشعار میں جستہ جستہ کیا ہے۔ مثلاًمذکورہ نظم کے حواشی میں لکھتے ہیں:
انگریزی مورخوں اور شاعروں کو جب یہ منظور ہوتا کہ لوگوں کو اپنی رحم دلی اور انسانی ہم دردی پر فریفتہ اور مسلمانوں پر غضب ناک اور بر افروختہ کریں تو وہ محمود غزنوی اور تیمور وغیرہ کی سختی اور تشدد کو خوب چھڑک چھڑک کر جلوہ گر کرتے ہیں۔۔۔جس طرح مگر مچھ، مچھلیوں اور مینڈکوں کو، یا شیر اور چیتا ہرن اور نیل گائے کو نوشِ جاں کرتا ہے اسی طرح جو انسان قوی اور زبر دست ہیں وہ ضعیف اور کم زور انسانوں کے شکار کرنے سے درگزر نہیں کرتے۔۔۔اگر کہیں آزادیِ تجارت میں کوئی مزاحمت پیش آتی ہے اور بغیر جبر و تعدی کے کام نہیں چلتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی شائستہ قوم بھی سب کچھ کرنے کو موجود ہوتی ہے۔۔۔ لیکن انصاف شرط ہے جن حکمتوں اور تدبیروں سے آج کل دنیا کی دولت گھسیٹی جاتی ہے، ان پر بر خلاف اگلے زمانے کی جابرانہ لوٹ کھسوٹ کے کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا۔(۳۸)
جب ہم حالی کے قصائد،سپاسیے اور وداعیے دیکھتے ہیں جو شاہزادہ ویلز،چارلس ایچیسن،جیمس لائل،مسٹر برور، مسٹر آرنلڈ،مسٹر ماریسن کے لیے لکھے گئے ہیں اور جن میں غیر معمولی مبالغے سے کام لیا گیا ہے،حال آنکہ کہ مقدمے میں حالی مبالغے کو شاعری کا سب سے بڑا عیب قرار دیتے ہیں، جب ہم ’’زمزمہ قیصری‘‘ کے حواشی میں ظاہر کیے جانے والے خیالات کے متوازی حالی کے یہ اشعار دیکھتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ حالی شر کا علم رکھتے ہیں،مگر اپنی قومی شاعری میں فقط’’ خیر‘‘ کے پہلو ہی پیش کرتے ہیں:
پاؤ گے تاریخ میں ہرگز نہ تم اس کی مثال
سلطنت نے قوم کی جو یاں مدد فرمائی ہے(۳۹)
گو منتِ قیصر سے ہے ہر قوم گراں بار
احساں مگر اسلام پہ اس کے ہیں گراں تر
معلوم ہیں جو موروں پہ اسپین میں گزری
جس وقت ازابیلا ہوئی واں صاحب افسر
حالت وہی ا س ملک میں پہنچی تھی ہماری
گڑتا نہ اگر اس کا نشاں ہند میں آکر
قیصر کے گھرانے پہ رہے سایہء یزداں
اور ہند کی نسلوں پہ رہے سایہء قیصر(۴۰)
ہر چندیہ ایک فلسفیانہ سوال ہے کہ خیر و شر اپنی مطلق حیثیت کے سوا ایک دوسرے میں شامل ہوسکتے ہیں،تاہم اگر ہم اسے حالی کی قومی شاعری کے تناظر میں دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شر میں خیر کی موجودگی ایک طرف شر کے خلاف مزاحمت سے بچنے کی کوشش ہے اور دوسری طرف اسے قابلِ قبول بنانے کی سعی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حالی یورپ کو ایک شر کے طور پر نہیں، ایک خیر کے طور پر لیتے ہیں،جس میں شر موجود ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ شر بھی یورپ کے خیر کے مرکز میں نہیں، اس کے حاشیے میں موجود ہے؛اس کی حقیقی شناخت نہیں،اس کی مجموعی شناخت کا ایک معمولی سا جزو ہے۔ چناں چہ حالی کی قومی شاعری میں یورپ اور انگریز ایک استعمار کی حیثیت میں ظاہر ہوتے ہی نہیں، اس لیے ان کے خلاف مزاحمت کے بجائے،ان کی مرعوبیت اور مدحت کا بیانیہ حالی کی قومی شاعری کی پہچان بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حالی اپنی قومی شاعری میں اس عوامی منطقے کو اقتداری حیثیت حاصل کرنے کا پورا موقع دیتے ہیں،جو یورپی تصورِ قوم سے عبارت ہے اور جس میں یورپ کبھی ’غیر‘ نہیں بنتا۔ کون نہیں جانتا کہ ہمیشہ ’غیر‘ ہی سے احتجاج،مزاحمت اور آزادی کی خواہش کی جاتی ہے!
حواشی
۱- شیخ عبدا لقادر، The New School of Urdu Literature،لاہور،پنجاب ابزرور پریس، ۱۸۹۸ء ص ۲
۲- کرنل ایف جے گولڈ سمڈ، ”On the Preservation of National Literature in the East”مشمولہ دی جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بریٹن اینڈ و آئرلینڈ، لندن، جلدا،ص۳۰
۳- ایضاً
۴- والٹر ڈبلیو سکیٹ،A Concise Etymological Dictionary of the English Language ،لندن، اوکسفرڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۲۷ء( ۱۸۸۲ء)، ص ۵۹۱
۵- ایچ۔ ڈبلیو۔ فائولر، A Dictionary of Modern English Usage، لندن، اوکسفرڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۲۷ء، ص ۳۰۸
۶- لیوس فرڈینینڈ سمتھ،(Lewis Ferdinand Smith) ترجمہ(انگریزی) باغ و بہار، لکھنئو، نول کشور پریس، ۱۸۹۵ء، ص ii
۷- شیخ عبدا لقادر، The New School of Urdu Literature، ص ۲۴
۸- ایضاً، ص ۲۵
۹- الطاف حسین حالی، دیوانِ حالی(مقدمہ شعر و شاعری پر)، کان پور، زمانہ پریس، ۱۸۹۳ء، ص ۵
۱۰- لوئی کزامیا(Louis Cazamian)،A History of English Literature(ترجمہ: ڈبلیو ڈی میکلینز)لندن،جے ایم ڈینٹ اینڈ سنز، ۱۹۵۷ء ص ۱۰۴۵
۱۱- الطاف حسین حالی، مجموعہ نظمِ حالی، دہلی، مطبع مرتضوی، ۱۸۹۰،ص ۲
۱۲- بینڈکٹ اینڈرسن، Imagined Communities: Reflections on the Origin of Nationalism، لندن و نیویارک، ورسو، ۱۹۹۱ء( ۱۹۸۳ء)، ص ۶
۱۳- علامہ اقبال،Stray Reflections (مرتّبہ ڈاکٹر جاوید اقبال)، لاہور، اقبال اکیڈمی، ۱۹۹۲ء (۱۹۶۱ء)، ص۱۱۰
۱۴- سیموئیل ٹیلرکالرج، Biographia Literaria، لندن، جے ایم ڈینٹ اینڈ سنز، ۱۹۵۲ء ص ۱۴۶
۱۵- الطاف حسین حالی، مجموعہ نظمِ حالی، ص ۲۵
۱۶- علامہ اقبال،Speeches and statements of Iqbal (مرتّبہ شاملو)، لاہور، اقبال پبلی کیشنز، س ن، ص۲۰۵
۱۷- گیاتری چکرورتی،Nationalism and Imagination،مشمولہ Nation in Imagination، مرتبہ : سی وجییسری،میناکشی مکھرجی،ہریش تریویدی، ٹی وجے کمار، حیدرآباد(بھارت)،اوینٹ لانگ مین، ۲۰۰۷ء، ص ۱
۱۸- الطاف حسین حالی، مجموعہ نظمِ حالی، ص ۲۵
۱۹- الطاف حسین حالی، مجموعہ نظمِ حالی، ص۹۴
۲۰- الطاف حسین حالی، مجموعہ نظمِ حالی، ص۹۱
۲۱- ایضاً، ص ۲۶
۲۲- ہینسلائی ویجورڈ(Hensleigh Wedgword)، A Dictionary of English Etymology جلد اوّل، لندن، ٹروبنر ایند کمپنی، ۱۸۵۹ء، ص a
۲۳- الطاف حسین حالی،ترکیب بند موسوم بہ شکوہء ہند، لاہور، صحابی پریس، ۱۸۸۸ء طبع ثانی، ص۱۰۔۔۲۲
۲۴- شیلڈن پولاک،Literary Cultures in History: Reconstruction from South Asia،لاس انجلس و لندن، کیلی فورنیا یونیورسٹی پریس،۲۰۰۳ء، ص ۴
۲۵- الطاف حسین حالی، مقالاتِ حالی (حصہء اول)، علی گڑھ، انجمن ترقی اردو ہند،۱۹۵۷ء ص ۱۳۳
۲۶- مولانا عبدالسلام ندوی، ابنِ خلدون، لاہور،گلوب پبلشرز،س ن، ص ۹۴
۲۷- الطاف حسین حالی، کلیاتِ نظمِ حالی(مرتبہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی) جلد دوم، لاہور، مجلسِ ترقیِ ادب، ۱۹۷۰ء، ص۵۹
۲۸- بپن چندر پال،The Spirit of Indian Nationalism،لندن، ہند نیشنلسٹ ایجنسی، س ن، ص ۱۲۔۔۱۳
۲۹- ایڈورڈ سعید، Orientalism ، پینگوئن بکس،۱۹۷۸ء، ص ۲۰
۳۰- الطاف حسین حالی، یادگارِ غالب، ص ۴۳۵
۳۱- الطاف حسین حالی، مجموعہ نظمِ حالی، ص ۲۷
۳۲- الطاف حسین حالی، مسدس حالی، ص ۷۲
۳۳- ایضاً، ص ۳۳
۳۴- الطاف حسین حالی، کلیاتِ نظمِ حالی(مرتبہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی)، جلد اول، ص ۴۵
۳۵- معین احسن جذبی، حالی کا سیاسی شعور، لاہور، آئینہ ادب، ۱۹۶۳ء ص ۱۲۴
۳۶- الطاف حسین حالی، کلیاتِ نظمِ حالی(مرتبہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی)،جلد اول، ص ۴۵
۳۷- ایضاً، ص ۴۶
۳۸- الطاف حسین حالی، مقالاتِ حالی (حصہ اول)، ص ۵۳ تا ۶۱
۳۹- الطاف حسین حالی، کلیاتِ نظمِ حالی(مرتبہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی)،جلد دوم، ص۲۰۰
۴۰- الطاف حسین حالی، کلیاتِ نظمِ حالی(مرتبہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی)،جلد اول،ص ۲۷۱۔ ۲۷۲