مستنصر حسین تارڑ
’’پیار کا شہر‘‘ سے شہرِ ویران تک
مستنصر حسین تارڑ گذشتہ ساٹھ سال سے اپنی تصنیفی اور تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی ابتدائی شناخت تو بطور سفرنامہ نگار بنائی اور اس کی انفرادیت اور شہرت ان کے بائیس سفرناموں کے ساتھ مستحکم ہوئی ہے۔ تخلیقی اعتبار سے سب سے اہم صنف جس میں انھوں نے مسلسل اپنے تخلیقی تجربے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ناول کی صنف ہے۔ ناول ایک ایسی نثری صنف ہے جس کا دامن بہت وسیع ہے اور جس میں متنوع النوع قسم کے تجربات کو سمونے کی بے پناہ طاقت ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے ناول کی صنف کے اس وصف کو بڑی خوبی سے برتا ہے۔
انفرادیت اور شہرت ان کے بائیس سفرناموں کے ساتھ مستحکم ہوئی ہے۔ تخلیقی اعتبار سے سب سے اہم صنف جس میں انھوں نے مسلسل اپنے تخلیقی تجربے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ناول کی صنف ہے۔ ناول ایک ایسی نثری صنف ہے جس کا دامن بہت وسیع ہے اور جس میں متنوع النوع قسم کے تجربات کو سمونے کی بے پناہ طاقت ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے ناول کی صنف کے اس وصف کو بڑی خوبی سے برتا ہے۔
مستنصر حسین تارڑ کی تخلیقی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو ۱۹۹۰ء کے بعد ان کی زیادہ توجہ صنف ناول پر مرکوز رہی ہے۔ اگرچے ان کی ناول نگاری کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا۔ ان کا پہلا قابل ذکر ناول ’’پیار کا پہلا شہر‘‘ ہے جو ۱۹۷۲ء میں شایع ہوا۔ اس ناول کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ اب تک اس کے پچاس سے زیادہ ایڈیشن شایع ہو چکے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ نے ناولوں کے ساتھ ساتھ دو ناولٹ ’’پکھیرو‘‘ (پنجابی) اور فاختہ (اردو) میں تخلیق کیے تھے۔ یہ دونوں ناولٹ اردو زبان میں ’’پرندے‘‘ کے نام سے شایع ہو چکے ہیں۔ ہم مستنصر حسین تارڑ کی ناول نگاری پر بات کا آغاز ’’پیار کا پہلا شہر‘‘ سے کرتے ہیں۔
’’پیار کا پہلا شہر‘‘ کی جڑیں ہمیں مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے ’’نکلے تری تلاش میں‘‘ میں دکھائی دیتی ہیں کہ جس میں ایک پورا ’’باب‘‘ ایک حقیقی کردار ’’پاسکل‘‘ کے بارے میں ہے۔ پاسکل ایک نیم اپاہج کردار ہے جس کا تحرک تخلیق کار کے ذہن پر گہرے نقش چھوڑتا ہے اور وہ اپنے دوست سرور سکھیرا کے اصرار پر اس باب کو ایک پورے ناول میں ڈھال دیتے ہیں۔ ’’پیار کا پہلا شہر‘‘ میں پاسکل کا کردار محبت کا استعارہ بن جاتا ہے اور پورے ناول میں ہمیں انسانی کرداروں اور انسانی جذبوں کے درمیان دلچسپ کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ ’’پاسکل‘‘ اور ’’سنان‘‘ کے درمیان محبت کا رشتہ ہے لیکن ’’سنان‘‘ کو اپنی سیاحت بھی بہت عزیز ہے۔ ’’پاسکل‘‘ کی جسمانی معذوری اس کے لیے کسی بھی سطح پر محتاجی نہیں بنتی اور وہ بڑی محنت سے زندگی کے سفر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ پاسکل کے کردار میں وہ سب کچھ ہے جیسے مثبت معنوں میں نسائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی محبت خالص ہے۔ اس میں معصومیت، سپردگی اور شدید وابستگی کے جذبات موجود ہیں اور وہ اپنی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ’’پاسکل‘‘ کے برعکس ’’سنان‘‘ دنیاداری میں ڈوبا ہوا مرد ہے اس لیے محبت کو نبھانے کی صلاحیت اس میں کم کم ہے وہ ’’پاسکل‘‘ کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس اپنے ملک چلا جاتا ہے۔ ’’پاسکل‘‘ اور ’’سنان‘‘ کے کردار نام بدل بدل کر تارڑ کے ناولوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔
’’پیار کا پہلا شہر‘‘ میں ایک رومانوی فضا موجود ہے۔ اس ناول کے جوان کردار اپنے اردگرد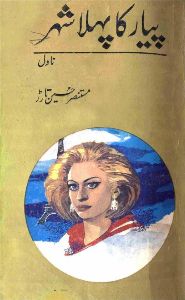 کی دنیا پر اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر اپنے تصورات میں گم ہو جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت ہے اور اس ناول کے کردار اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتیں انھیں خوشیاں دیتی ہیں۔ ناول نگار نے اپنے خوبصورت زبان و بیان سے ناول میں ایسی دلچسپی پیدا کر دی ہے کہ پڑھنے والا اس سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔
کی دنیا پر اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر اپنے تصورات میں گم ہو جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت ہے اور اس ناول کے کردار اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتیں انھیں خوشیاں دیتی ہیں۔ ناول نگار نے اپنے خوبصورت زبان و بیان سے ناول میں ایسی دلچسپی پیدا کر دی ہے کہ پڑھنے والا اس سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔
’’دریا کی سطح پہلے کی طرح پر سکون تھی مگر غبار کی ہلکی تہ جو دوپہر کو پانی کے اوپر معلق تھی اب موجود نہیں تھی۔ سورج کی کرنوں میں پیلاہٹ کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ پاسکل اپنے پاؤں کو خم دے کر کنارے کی گدلی مٹی ناخنوں سے کریدتی تو وہ کیچڑ آلود ہو جاتا۔ پھر وہ اپنا لباس اوپر کھینچ کر پاؤں پانی میں ڈال کر ہلاتی تو کیچڑ دریا کی سست رو لہروں سے آہستہ آہستہ گھلتا اور اس کا شفاف پاؤں دھل کر ایک سفید مچھلی کی طرح تیرنے لگتا۔‘‘ (پیار کا پہلا شہر، ۲۰۰۴ء، ص:۱۹۱)
’’پیار کا پہلا شہر‘‘ مستنصر حسین تارڑ کے کام میں اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں ہمیں ان کے تخلیقی تجربے کی کئی جہات اپنے سامنے کھلتی نظر آتی ہیں اور رفتہ رفتہ آگے چل کر ان کے ناولوں میں یہی تخلیقی تجربہ اپنی متنوع شکل میں سامنے آتا ہے۔ محبت انسان کا ازلی و ابدی تجربہ ہے جسے اربوں بار دُہرایا گیا ہے مگر یہ پرانا نہیں ہوا بلکہ اگر ایک ہی انسان اس تجربے کو بار بار دہرائے تو یہ تب بھی میلا اور پرانا نہیں ہوتا۔ محبت کے تجربے کے اتنے رنگ ہمیں مستنصر حسین تارڑ کے ناولوں میں دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا ناول نگار کم ہی ان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
’’پیار کا پہلا شہر‘‘ کے بعد مستنصر حسین تارڑ نے ’’جپسی‘‘ تخلیق کیا۔ ’’جپسی‘‘ کے پس منظر میں بھی ہمیں ان کا ایک اور سفرنامہ ’’خانہ بدوش‘‘ دکھائی دیتا ہے۔ ’’جپسی‘‘ میں ہمارا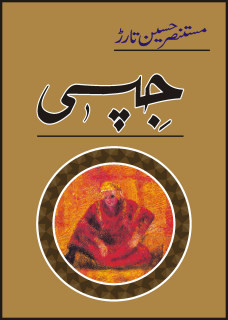 سامنا ایسے کرداروں سے ہوتا ہے جو اپنے منہ زور جذبات کی تسکین کو اولیت دیتے ہیں اور کسی بھی تہذیبی ضابطے اور معاشرتی قدر کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے لیکن اس ناول میں کوئی کردار ’’پاسکل‘‘ کی طرح طاقتور اور یاد رہ جانے والا نہیں ہے۔ اس ناول میں بھی ایسا مواد موجود ہے جو ہمیں خود ناول نگار کی زندگی کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ناول میں یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ ناول نگار آپ بیتی بھی لکھتا ہے اور جگ بیتی بھی مگر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کس خوبی سے اس سب کو ناول کے بیانیے کا حصہ بناتا ہے۔
سامنا ایسے کرداروں سے ہوتا ہے جو اپنے منہ زور جذبات کی تسکین کو اولیت دیتے ہیں اور کسی بھی تہذیبی ضابطے اور معاشرتی قدر کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے لیکن اس ناول میں کوئی کردار ’’پاسکل‘‘ کی طرح طاقتور اور یاد رہ جانے والا نہیں ہے۔ اس ناول میں بھی ایسا مواد موجود ہے جو ہمیں خود ناول نگار کی زندگی کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ناول میں یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ ناول نگار آپ بیتی بھی لکھتا ہے اور جگ بیتی بھی مگر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کس خوبی سے اس سب کو ناول کے بیانیے کا حصہ بناتا ہے۔
مستنصر حسین تارڑ کا تیسرا ناول ’’دیس ہوئے پردیس‘‘ بنیادی طور پر بیسویں صدی کے ایک نہایت ہی اہم تجربے یعنی تلاشِ زرق کے لیے پردیس جانے اور وہاں کے ثقافتی مغائرت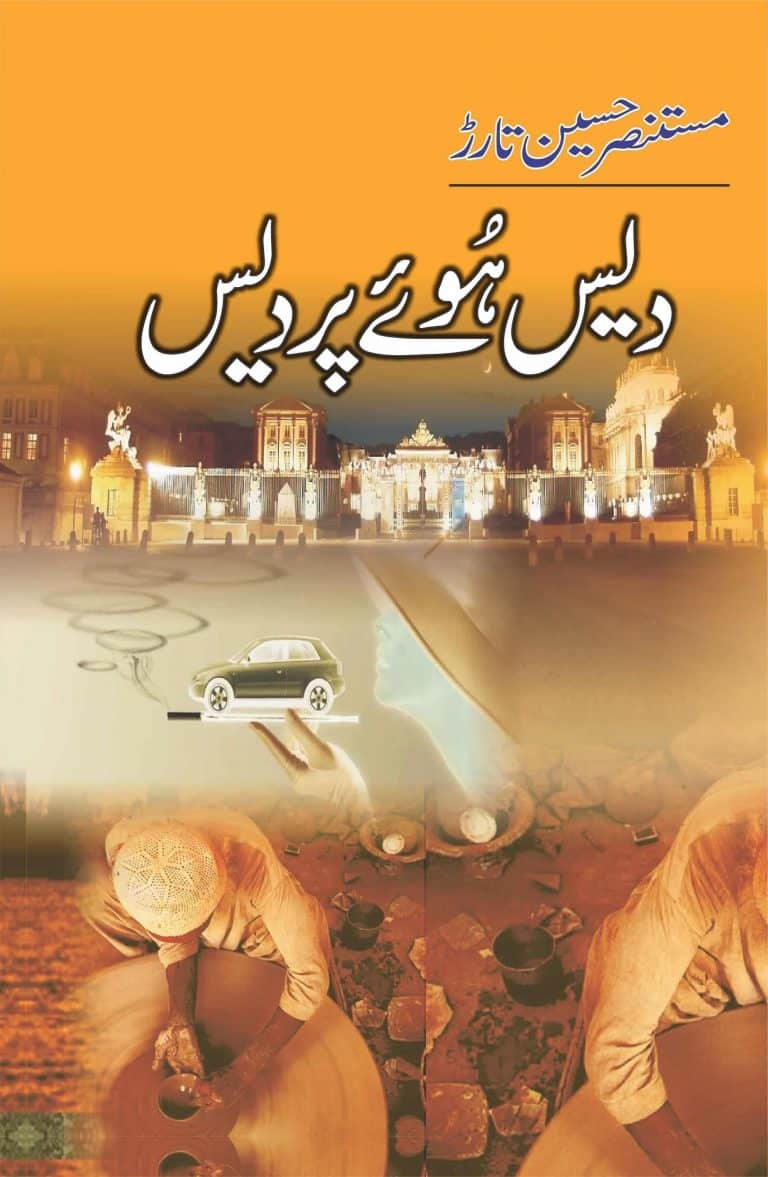 کے تجربے کو سہارنے سے عبارت ہے۔ ’’دیس ہوئے پردیس‘‘ کے کردار دوسرے دیس میں جا کر بس تو گئے ہیں لیکن انھوں نے ابھی پوری طرح وہاں کی بودوباش اختیار نہیںکی۔ یہ تارکین وطن کی پہلی نسل کی روداد ہے اور اس نسل کے معاشرتی اور نفسیاتی رویوں کو سمجھنے کی کوشش۔ اس سب کے باوجود اس ناول کو تارڑ کے تخلیقی سفر میں کچھ زیادہ اہمیت حاصل نہیں کیوںکہ اس میں جو کچھ ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے تارڑ کے بعد کے ناول میں آیا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا ناول ’’بہاؤ‘‘ ان کے تخلیقی تجربے میں ایک نہایت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔
کے تجربے کو سہارنے سے عبارت ہے۔ ’’دیس ہوئے پردیس‘‘ کے کردار دوسرے دیس میں جا کر بس تو گئے ہیں لیکن انھوں نے ابھی پوری طرح وہاں کی بودوباش اختیار نہیںکی۔ یہ تارکین وطن کی پہلی نسل کی روداد ہے اور اس نسل کے معاشرتی اور نفسیاتی رویوں کو سمجھنے کی کوشش۔ اس سب کے باوجود اس ناول کو تارڑ کے تخلیقی سفر میں کچھ زیادہ اہمیت حاصل نہیں کیوںکہ اس میں جو کچھ ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے تارڑ کے بعد کے ناول میں آیا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا ناول ’’بہاؤ‘‘ ان کے تخلیقی تجربے میں ایک نہایت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔
’’بہاؤ‘‘ نے تارڑ کو سنجیدہ ادبی حلقوں میں موضوعِ بحث بنایا۔ ’’بہاؤ‘‘ کی تخلیق یقینا اردو میں ایک اہم اور منفرد واقعہ تھی۔ ’’بہاؤ‘‘ کا موضوع آج سے تین ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کو شروع ہوئے ایک ہزار سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور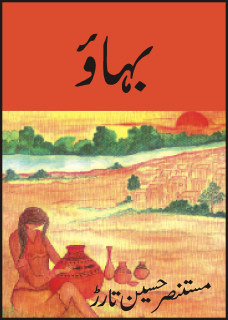 یہاں کے قدیم تہذیبی مراکز اپنی حیات کے آخری سانس لے رہے تھے۔ ایک قدیم تہذیب کو موضوع بناتا یہ ناول دراصل کسی موجود مظہر کو پیش کرنے کی کوشش نہیں تھا جیسا کہ بیشتر تاریخی ناولوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسی تہذیب کو تخلیق کرنے کی کوشش تھا جو مدت ہوئی کرہ ارض سے معدوم ہو چکی اور اس کی بہت کم باقیات ہم تک پہنچی ہیں۔ یوں ’’بہاؤ‘‘ تاریخی نہیں ایک تہذیبی ناول ہے۔
یہاں کے قدیم تہذیبی مراکز اپنی حیات کے آخری سانس لے رہے تھے۔ ایک قدیم تہذیب کو موضوع بناتا یہ ناول دراصل کسی موجود مظہر کو پیش کرنے کی کوشش نہیں تھا جیسا کہ بیشتر تاریخی ناولوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسی تہذیب کو تخلیق کرنے کی کوشش تھا جو مدت ہوئی کرہ ارض سے معدوم ہو چکی اور اس کی بہت کم باقیات ہم تک پہنچی ہیں۔ یوں ’’بہاؤ‘‘ تاریخی نہیں ایک تہذیبی ناول ہے۔
وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا شمار دنیا کی چند ابتدائی تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ہڑپہ اور موہنجوداڑو سے برآمد ہونے والے آثار ہمیں اس زمانے کے لوگوں کے رہن سہن کا پتہ دیتے ہیں۔ لیکن ’’بہاؤ‘‘ کا موضوع ان شہروں کی تہذیب نہیں بلکہ دریائے گھاگھر ایا سرسوتی کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو قدیم تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ قدیم تہذیب اپنے آخری سانس گن رہی ہے۔ یہ گاؤں تھوڑے سے نفوس پر مشتمل ہے۔ اس گاؤں کا کوئی نام نہیں۔ گاؤں کی تہذیب مادر سری تہذیب ہے جس کا مرکز عورت کی ذات ہے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر ہے۔ قانون اس گاؤں سے دور بہتا ہے اور جنس ابھی سماجی ٹیبو نہیں بنی۔ مذہب نہایت سادہ نوعیت کا ہے۔
’’پاروشی‘‘ اس ناول کا مرکزی کردار ہے جسے مصنف نے نہایت چابکدستی سے تراشا ہے۔ پاروشی جو گھاگھرا کی بیٹی ہے اور جسے گاؤں کی ایک عورت ماتی نے پالا ہے۔ پاروشی جب جوان ہو کر اپنا الگ گھر بناتی ہے تو اس کی زندگی میں دو مرد آتے ہیں ورچن اور سمرو۔ دونوں اپنی عادات و اطوار میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن پاروشی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پاتی۔ پاروشی اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے دراوڑی نسل کا شاہکار ہے۔ حسیاتی سطح پر زندہ ہے۔ حسیات پاروشی کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مادرسری تہذیب کے لوگ زمین کے ساتھ مضبوط تعلق بنا کر رہتے ہیں۔ یہ عقل و خرد اور منطقی علوم کی دنیا سے پہلے کے باسی، اپنے اردگرد کے مظاہر سے ہم آہنگ زندگی گزارتے ہیں۔ مگر یہی کردار جب ’’بہاؤ‘‘ میں بہت عمدہ طریقے سے تراشے ہوئے فکری سوال اٹھاتے ہیں تو ناول کی فضا مصنوعی ہو جاتی ہے۔
ناول میں بنیادی کردار دریائے گھاگھرا کا ہے۔ دریائے گھاگھرا کا پانی حیات اور تہذیب دونوں کو قائم رکھے ہوئے ہے مگر اب یہ دریا رفتہ رفتہ سوکھ رہا ہے۔ پاروشنی جو گھاگھرا کی بیٹی ہے۔ بیک وقت تہذیب اور دریا دونوں کی علامت بنتی ہے۔ بستی جوہر حیات پانی سے محروم ہو رہی ہے۔ دریا سوکھ رہا ہے لیکن اس کے کنارے آباد لوگ ابھی اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ بستی سے دس کوس کے فاصلے پر موجود جھیل بھی سوکھ رہی ہے۔ ریت قدم بہ قدم بستی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سب علامتیں بنجر پن کی ہیں۔ ناول کا مرکزی کردار ’’پاروشنی‘‘ بھی اسی نوعیت کی صورتحال سے دو چار ہے۔ وہ اپنے لیے مرد کا انتخاب کرنے سے قاصر ہے۔ ورچن بستی کا پہلا مرد ہے جو دور دیس کی سیر پر نکلتا ہے اور تحرک اور فعلیت کا استعارہ بنتا ہے۔ جبکہ سمرو ایک تخلیق کار ہے۔ دونوں متضاد خصوصیات کے حامل ہیں اور پاروشنی دونوں کے لیے لگن رکھتی ہے۔ ورچن جب لمبے سفر سے لوٹتا ہے تو پاروشنی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہی دونوں میں سے بہتر ہے مگر شب زناف ورچن اسے بیدار کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ سمرو کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی علامتی سطح پر اس وقت کی تہذیب میں تحرک اور فصیلت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ جب پاروشنی مرد ہ بچہ جن کر اسے دریائے گھاگھرا کے حوالے کر دیتی ہے تو تخلیق کے عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیتی ہے اور تب دریائے گھاگھرا میں بڑے پانی آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناول میں جگہ جگہ لمبے لمبے مکالمے ہیں جیسے ص ۵۶ سے ص ۷۰ تک ورچن اور پورن کے درمیان ہونے والا مکالمہ جو دو تہذیبوں کے درمیان مکالمہ بن جاتا ہے۔ ایک سطح پر یہ بالادست اور زیر دست طبقوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ بھی ہے۔ نئے آنے والے جو اپنی عقل اور طاقت کے زور پر ہر علامت اور نشان کو بدل رہے ہیں اور یہاں کے قدیم باشندے جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ مکالمے کے آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ ورچن اور پورن میں کچھ بھی مشترک نہیں۔ یا پھر ورچن اور ’’ڈورگا‘‘ کے درمیان ہونے والی بات چیت۔ ’’ڈورگا‘‘ جس کے پرکھوں میں سے کسی نے خود کو آرام کی روٹی کھانے کے لیے اینٹوں کے بھٹے کے مالک کے پاس گروی رکھ دیا تھا اور اب نسلیں اس کا قرض ادا کر رہی ہیں۔ چار دیواری میں محبوس زندگی کرتے ہوئے لوگوں میں سے ’’ڈورگا‘‘ وہ آدمی ہے جو باہر کی دنیا سے رابطہ استوار کرنا چاہتا ہے۔ ورچن، پورن اور ڈورگا تین مختلف طبقوں کے نمائندہ ہیں۔ اس لیے تینوں مختلف زبان بولتے اور مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں مگر ان مکالموں میں ناول نگار کی موجودگی بہت محسوس ہوتی ہے۔
ورچن اور ڈورگا جب واپس بستی کو لوٹ رہے ہیں تو راستے میں ایسی بستیوں کے آثار ملتے ہیں جو کبھی تھیں اور اب مِٹ چکی ہیں۔ ورچن ان بستیوں کی تباہی کا ذمہ دار باہر سے آنے والوں کو قرار دیتا ہے لیکن ڈورگا کہتا ہے کہ بستیاں باہر سے نہیں اندر سے مرتی ہیں۔ ’’وہ لوگوں کے کڑھنے سے مرتی ہیں…… اندر ہی اندر بوڑھے مجھ ایسے اور بچے بھوکے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے اور عورتیں جو میرے ایسوں کو جنم دیتی ہیں تو یہ سب کڑھتے ہیں کہ ہم ایسے کیوں ہیں اپنے اندر سے سوچتے ہیں کہ ہمیں ہزار برس کی قید کیوں ہے۔‘‘ پتہ نہیں ایک چاردیواری میں زندگی بسر کرنے والا ڈورگا ایسی حکمت کہاں سے سیکھ جاتا ہے۔
’’بہاؤ‘‘ میں گھاگھرا کے کنارے آباد بستی کے پہلو میں وسیع جنگل ہے جس میں جانور اور پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ اس جنگل میں بستی کا ایک باسی ’’مامن ماسا‘‘ بھی رہتا ہے۔ جنگل بستی سے جڑا اور بستی کے رہنے والوں کی زندگی کا جزو لاینفک ہے۔ اسی جنگل میں ایک بھینسا ہے جس کی طاقت سے سب خوفزدہ ہیں لیکن جو کم ہی کسی کو دکھائی دیتا ہے۔ بھینسا ایک بارڈورگا کو ادھیڑ چکا ہے مگر ڈورگا مسلسل اس کی پکار سنتا ہے اور اس سے میل کرنے جانا چاہتا ہے۔ بھینسا طاقت کی علامت ہے لیکن جب ناول کے آخر میں ڈورگا اسے ختم کر دیتا ہے تو یہ ہمیں ناول نگار کی رجائیت کا اظہار معلوم ہوتا ہے کیوںکہ بظاہر خارجی سطح پر اس کے امکانات نہ تو ناول میں موجود تھے نہ آج کی دنیا میں نظر آتے ہیں۔
بحیثیت مجموعی طور پر تارڑ نے اس ناول کو نہایت اچھے انداز سے بُنا ہے۔ وہ قدیم عہد کی فضا پیدا کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے اور اس فضا کو تخلیق کرنے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی بہت برمحل اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ قرآت کے اعتبار سے یہ ایک مشکل ناول ہے۔ پڑھنے والے کو اس فضا، ماحول اور زبان سے خود کو مانوس کرنا پڑتا ہے مگر ایک بار یہ ہو جائے تو پھر ناول پڑھنے والے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یہ ناول نگار کی بڑی کامیابی ہے۔
’’بہاؤ‘‘ میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو ناول کی پوری فضا سے مطابقت نہیں رکھتیں اور ناول کے حسن کو متاثر کرتی ہیں۔ مثلاً سندھ کے کنارے آباد شہر کو موہنجوداڑو لکھا گیا ہے۔ موہنجوداڑو جدید سندھی نام ہے جس کے معنی مردوں کا ٹیلا ہے۔ ظاہر ہے آج سے تین ہزار سال قبل کے لوگ اپنے شہر کو مردوں کاٹیلہ تو نہیں کہتے ہوں گے۔ اسی طرح ناول میں دریا میں بڑے پانی آنے پر گندم کی کاشت کروائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ گندم جولائی، اگست میں نہیں اکتوبر نومبر میں کاشت ہوتی ہے۔ دوسرا کھیتوں میں کھڑا پانی گندم کی کاشت کے لیے لازمی نہیں۔ تخیلاتی سطح پر آپ گندم مئی جون میں بھی کاشت کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جس مہارت اور فنی چابکدستی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں اس ناول میں نظر نہیں آتی۔
اسی طرح ایک بات ماتی کے تین بیٹوں کے حوالے سے ہے۔ ناول کے ص۱۲ پر آتا ہے کہ ’’وہ تینوں جھوریا تھے۔ پہلا دوجا اور تیجا جھوریا‘‘ جبکہ ص ۹۹ پر تینوں کے الگ الگ نام ’’وانگو‘‘، چیوا‘‘ اور ’’جھوریا‘‘ درج ہیں۔ اس طرح کی اغلاط اگرچہ معمولی نوعیت کی ہیں لیکن تخلیقی ذمہ داری سے گریز کو ظاہر کرتی ہیں۔ جن سے ناول کا حسن متاثر ہوتا ہے۔
جیسا کہ میں نے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ ’’بہاؤ‘‘ ایک تہذیبی ناول ہے اور اس میں تارڑ نے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کو تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ وادی سندھ کے بارے میں یہ خیال کافی پرانا ہے کہ اس تہذیب کا گنگا وادی کی تہذیب سے زیادہ تعلق نہیں ہے بلکہ اس تہذیب کے مٹنے اور گنگا وادی کی تہذیب کی تشکیل کا عمل شروع ہونے میں زمانی بعد موجود ہے۔ شمال سے آنے والے حملہ آوروں کے باعث وادی سندھ کے باشندوں کو جنوب کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ تب گنگا وادی میں تہذیبی ترقی کا عمل شروع ہوا۔ پاکستان میں ۱۹۷۱ء کے سانحے کے بعد یہاں کی تہذیب کو جغرافیائی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوا۔ سبط حسن کی کتاب ’’پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء‘‘ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ یحییٰ امجد کی تاریخ پاکستان کی دو جلدیں اسی تصور کو آگے بڑھاتی ہیں اور اعترازاحسن کے Indus Saga کو اسی ذیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ تحقیق سے قطع نظر تخلیقی سطح پر وادی سندھ کو بیان کرنے کی پہلی کامیاب کوشش تارڑ نے اپنے ناول ’’بہاؤ‘‘ میں کی ہے۔
’’بہاؤ‘‘ کے بعد تارڑ کا دوسرا ناول ’’راکھ‘‘ ہے جو ۱۹۹۷ء میں منظر عام پر آیا اور یہ قیام پاکستان سے ۱۹۹۲ء تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ تارڑ کا یہ ناول معاصر تاریخ و تہذیب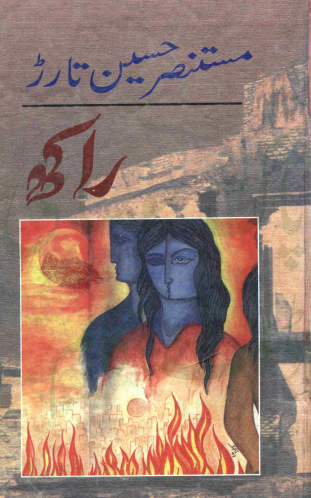 کو تخلیقی جہت سے گرفت میں لینے کی بہت اچھی کوشش ہے۔ تارڑ نے قیام پاکستان کے وقت لاہور میں ہونے والے فسادات اور پھر ۱۹۹۲ء میں بابری مسجد کی شہادت کے ردعمل میں پاکستان میں مندروں کے گرائے جانے کے واقعہ کو ملا کر ایک دائرہ ترتیب دیا ہے۔ اس ناول میں پاکستان کی تاریخ کے اہم سیاسی واقعات، برسر اقتدار طبقے کی چالبازیاں، منافقتیں اور سازشیں مشرقی پاکستان کا المیہ، کراچی کے لسانی فسادات، پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک، پاکستان اور بھارت میں مذہبی تنگ نظری اور تشدد کی لہر اور اس سارے سماجی تناؤ سے فرد کی شخصیت کے بکھرتے تارو پود کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
کو تخلیقی جہت سے گرفت میں لینے کی بہت اچھی کوشش ہے۔ تارڑ نے قیام پاکستان کے وقت لاہور میں ہونے والے فسادات اور پھر ۱۹۹۲ء میں بابری مسجد کی شہادت کے ردعمل میں پاکستان میں مندروں کے گرائے جانے کے واقعہ کو ملا کر ایک دائرہ ترتیب دیا ہے۔ اس ناول میں پاکستان کی تاریخ کے اہم سیاسی واقعات، برسر اقتدار طبقے کی چالبازیاں، منافقتیں اور سازشیں مشرقی پاکستان کا المیہ، کراچی کے لسانی فسادات، پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک، پاکستان اور بھارت میں مذہبی تنگ نظری اور تشدد کی لہر اور اس سارے سماجی تناؤ سے فرد کی شخصیت کے بکھرتے تارو پود کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
’’راکھ‘‘ میں تارڑ نے اچھے اور مضبوط کردار تراشے ہیں۔ مشاہد، مردان، زاہد کالیا، ڈاکٹر ارشد، فاطمہ اور برگیتا مضبوط کرداروں کی ذیل میں آتے ہیں جو اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ جوانی کی امنگوں سے بھرے توانا لوگ وقت اور سماجی دباؤ کے سامنے اندر ہی اندر سلگتے ہوئے ’’راکھ‘‘ کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ سوال کہ آخری نتیجہ کیا ہے، ناول کے کرداروں کا پیچھاکرتا ہے اور ناول نگار کا جواب ہے چہروں پر بکھرتی راکھ۔
تارڑ کے ناول میں واقعات کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ تاریخ جلد جلد ہمارے سامنے اپنے ورق پلٹتی ہے۔ مگر تقدیر کا جبر ہر کردار کو بے بس بنائے ہوئے ہے۔ عرب مسلمان لڑکی فاطمہ اپنا مذہب بدل کر بھی ملیچھ ہی رہتی ہے اور برگیتا کامونکی میں پیدا ہو کر سویڈن میں پرورش پاتی ہے لیکن آخر میں لاہور اس کی مستقل جائے سکونت بنتا ہے۔ زاہد کالیا پاکستان سے بدھ اور سکھ عہد کے نوادرات باہر سپلائی کرتا ہے اور وہاں سے اسلامی نوادرات لاتا ہے کہ کسی کو تو اپنی تہذیب کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دنیا ہے۔ مشاہد اور مردان ہیں جو اس بنتی بگڑتی تاریخ کے گواہ ہیں اور جن کے گرد ناول کے دوسرے کردار گردش کرتے ہیں۔ اس ناول میں لوگ اپنی جڑوں سے اکھڑتے ہیں اور پھر انھیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ بس اک سیل بے اماں ہے جس میں سب کچھ بہتا چلا جاتا ہے۔
’’راکھ‘‘ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کردار بھی ہیں۔ المیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے مسز بابر اور ان کی بیٹیاں اور شوبھا یا لکشمی مینشن کے اردگرد آباد قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں کے لوگ۔ یہاں تارڑ نے بعض نامور ادیبوں کے اصل نام استعمال کیے ہیں لیکن ہمیں انھیں فکشن کے کرداروں کے طور پر دیکھنا ہو گا ورنہ گمراہ کن قیاسات اور نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ مجھے تارڑ کی ایک بات نے متاثر کیا ہے کہ وہ معاصر تاریخ کو فاصلے سے دیکھتے ہیں اور بے جا جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے۔ اگرچہ بعض جگہ اس کے اس ناول میں عمومی نفسیات کی جھلک بڑی نمایان دکھائی دیتی ہے۔
’قربت مرگ میں محبت‘‘ ایک سطح پر پہلے دونوں ناول سے مربوط ہے اور (Triology) کو مکمل کرتا ہے۔ دریائے سندھ کے پانیوں پر جنم لیتی اس کہانی میں بار بار فلیش بیک کی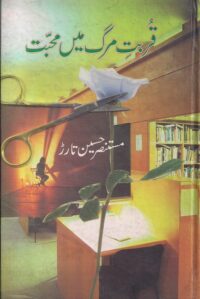 تکنیک سے خاور کی گزری زندگی کے واقعات بیانیہ میں در آتے ہیں۔ کچھ واقعات بیانیہ میں اچھی طرح سموئے گئے ہیں اور چند ایک غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں جیسے خاور کے بچپن کے واقعہ کا تفصیلی بیان۔ دریا جو زندگی ’’بہاؤ‘‘ اور تسلسل کی علامت ہے۔ دریا کا پونگ سرور، جعفر اور پکھی تینوں نے اونچی ناک والوں کی نظر سے بچ کرتین ہزار سال دریائے سندھ کے کنارے گزار دے۔ دریائے گھاگھرا سوکھا تو خشکی کے ان باسیوں نے دریائے سندھ پر بسیرا کر لیا۔ یہ دراوڑی نسل کے لوگ اپنے خدوخال ہی نہیں اپنے ثقافتی نقوش بھی بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اگرچہ تین ہزار سال سے ان کا استحصال جاری ہے کشتی کو دریا میں ڈھلتے یہ جنور بندے اپنا الگ مزاج، نفسیات اور بود و باش رکھتے ہیں۔ فطرت کی آغوش میں پرورش پاتے، فطرت سے ہم آہنگ زندگی کرتے یہ نفوس خاور کو ایک ایسے سفر پر لیے جاتے ہیں جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔
تکنیک سے خاور کی گزری زندگی کے واقعات بیانیہ میں در آتے ہیں۔ کچھ واقعات بیانیہ میں اچھی طرح سموئے گئے ہیں اور چند ایک غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں جیسے خاور کے بچپن کے واقعہ کا تفصیلی بیان۔ دریا جو زندگی ’’بہاؤ‘‘ اور تسلسل کی علامت ہے۔ دریا کا پونگ سرور، جعفر اور پکھی تینوں نے اونچی ناک والوں کی نظر سے بچ کرتین ہزار سال دریائے سندھ کے کنارے گزار دے۔ دریائے گھاگھرا سوکھا تو خشکی کے ان باسیوں نے دریائے سندھ پر بسیرا کر لیا۔ یہ دراوڑی نسل کے لوگ اپنے خدوخال ہی نہیں اپنے ثقافتی نقوش بھی بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اگرچہ تین ہزار سال سے ان کا استحصال جاری ہے کشتی کو دریا میں ڈھلتے یہ جنور بندے اپنا الگ مزاج، نفسیات اور بود و باش رکھتے ہیں۔ فطرت کی آغوش میں پرورش پاتے، فطرت سے ہم آہنگ زندگی کرتے یہ نفوس خاور کو ایک ایسے سفر پر لیے جاتے ہیں جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔
تارڑ اس ناول میں جہاں دراوڑی نسل کے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اکثر ان کے لیے جنور کا لفظ استعمال کر دیتا یا دیگر حیوانی خصوصیات ان سے متعلق کر دیتا ہے۔ ان کا کھانا پینا، گانا بجانا، موج مستی کرنا اور سرور اور پکھی کا ایک دوسرے سے ہم بستری کرنا، سب میں ایک حیوانی پن بیان کیا گیا ہے۔ دراوڑی نسل کے لوگوں کے ساتھ حیوانی خصوصیات منسلک کرنے کی ایک توجیہہ تو یہ کی جا سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ان لوگوں کو انھی الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور ناول نگار نے اجتماعی سماجی نفسیات کی عکاسی کی ہے لیکن میرے خیال میں بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ہمیں اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی نفسیات بھی جھلک مارتی دکھائی دیتی ہے۔ تارڑ کا نسلی تعصب بار بار اس کی تخلیقی ذات کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ کشتی کے سفر میں ڈھلتے یہ انسان دو مختلف نسلوں، تہذیبوں اور طرز زندگی کے استعارے بنتے ہیں۔ ناول نگار نے خاور یا شہری تمدن کے دوسرے کرداروں کے ساتھ حیوانی خصوصیات بالکل منسلک نہیں کیں۔ اگرچہ ناول کی سطح تک ان کے طرز عمل میں زیادہ فرق نہیں ہے۔
خاور جو اپنی زندگی کے آخری برسوں میں تین عورتوں کی قربت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ تینوں موت اور محبت کے حوالے سے اس کے نزدیک آتی ہیں اور پھر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ تین عورتیں جو اپنی اپنی سطح پر زندگی کا ایک ایک دور گزار چکی ہیں، خاور کو اپنی ذات کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ اپنے گھر کی تباہی کے بعد خاور ایک ایسے سفر پر نکلتا ہے جو زندگی کی طرح لاحاصل ہے اور ان تین جنور بندوں اور فہم کے درمیان تعلق اور لاتعلقی کی ایک عجیب زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو کسی کے لیے بھی کوئی معنویت نہیں رکھتی مگر وقتی ضرورتوں نے سب کرداروں کو ایک جگہ جوڑ دیا ہے۔
تارڑ کے اس ناول کی بنت پر ہمیں اس کے سرناموں کے بہت زیادہ اثرات ملتے ہیں۔ یہ اثرات صرف سفر کی بنیادی موٹیف تک محدود نہیں بلکہ جگہ جگہ ہمیں مشہور زمانہ ادب کے لیے درکار مصالے بیانیہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے پہلے دو ناولوں میں بھی تارڑ نے ناول کے بیانیہ کے لیے سفر نامے کی تکنیک سے استفادہ کیا تھا لیکن ’’قربت مرگ میں محبت‘‘ کے بیانیہ میں یہ استفادہ ناول کے بیانیے پر چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ناول کو ایک دائرے کی شکل میں بنا گیا ہے جو ’بہاؤ‘‘ سے بالکل مختلف انداز ہے۔ بہاؤ سیدھے خط پر سفر تھا جبکہ راکھ میں ناول کا بیانیہ تو سیدھے خط پر تھا مگر واقعات کی مماثلت نے دائرے کی کیفیت پیدا کر دی تھی جبکہ تیسرے ناول میں تو ناول نگار نے آغاز اور انجام ایک ہی واقعے پر کیے ہیں۔ شاید ناول کے موضوع کی وضاحت کے لیے اسے یہی تکنیک مناسب معلوم ہوئی ہے۔
تارڑ نے اپنے تینوں ناولوں میں کئی مماثلتیں ارادتاً پیدا کی ہیں۔ جیسے دریا کا بہاؤ، گھاگھرا سوکھ چکا ہے۔ راوی سوکھ رہا ہے اور سندھ کے سوکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ گھاگرا کی تہذیب فنا کے گھاٹ اتر چکی۔ راوی اور سندھ کے کنارے آباد تہذیب بھی زوال پذیر ہے لیکن ابھی یہاں کے باشندے اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ ’’بہاؤ‘‘ میں ریت تہذیب کے آثار کو نگل رہی ہے۔ ’’راکھ‘‘ میں راکھ چیزوں کے نقوش مٹا رہی ہے اور ’’قربت مرگ میں محبت‘‘ میں بلڈوزڈ گھروں کو مسمار کرتےہیں۔ تہذیب خود اپنے اندر سے مٹ رہی ہے کھوکھلی ہو چکی ہے اور اس تہذیب کی نمائندہ تینوں خواتین زندگی کے صحرا میں بھٹک رہی ہیں۔
برگیتا، پاروشنی کا جدید روپ تھی۔ تین ہزار سال کی مسافت میں اس نے اپنے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپنا سیکھ لیا تھا لیکن جس کا بدن ہوا اور پانی کے لمس کو براہ راست محسوس کرنے کی شدید لپک رکھتا تھا۔ برگیتا کا صرف سیاہ رنگ ہی نہیں اس کے جسم کا کساؤ بھی پادرشی کی یاد دلاتا ہے۔ دریائے گھاگھرا کے خشک ہونے کے بعد اس کے قبیلے کا کوئی فرد دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان آباد ہو گیا تھا۔ پکھی اسی پاروشنی کی تصویر ہے جو زمانی بعد کے باوجود تہذیبی اعتبار سے اپنی اصل پر قائم ہے۔ بدن جس کے لیے استعمال کی چیز ہے اور جو خاور کی بے رخی کو اپنی توہین سمجھتی ہے۔ جدید تہذیب کی نمائندہ تینوں خواتین کے برعکس قاری کو پکھی کا کردار زیادہ توانا نظر آتا ہے اگرچہ پکھی کا اظہار بالواسطہ طور سے ہوا ہے۔
’’قربت مرگ میں محبت‘‘ میں ایک بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تارڑ نے اس ناول میں ’’بہاؤ‘‘ کے ساتھ مماثلتیں پیدا کرنے کی شعوری کوششیں کی ہیں۔ مثلاً ’’مامن ماسا‘‘ جو اس دور کی باتیں بھی جانتا ہے جب یہ لوگ ایک دور دراز کے علاقے میں آباد تھے۔ یا مور کی پکار یا پکھی اور پاروشنی کا تقابل یا سرور اور ورچن اور سمرو کا تقابل۔ میری ذاتی رائے میں ان شعوری کوششوں سے ناول کے بیانیہ میں کوئی قوت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک نوع کی کمزوری در آتی ہے اور یہ اشارے ناول کے موضوع کو آگے بڑھانے میں کوئی زیادہ معاون ثابت نہیں ہوتے۔
’’قربت مرگ میں محبت‘‘ پہلے کے دو ناولوں کے مقابلے میں فنی اور فکری اعتبار سے کمزور محسوس ہوتا ہے۔ ناول نگار اس ناول کو اس پختگی سے تحریر نہیں کر سکا جو اس نے پہلے دونوں ناولوں میں برتی تھی۔ اس ناول کا موضوع محبت اور موت میں موجود مماثلت کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک سطح پر جنس اور موت کی جبلت میں بھی گہرا تعلق پایا جاتا ہے لیکن ناول کے بیانیے میں یہ تعلق پوری جامعیت سے نہیں آ پایا۔ اگرچہ تارڑ نے اپنے دلچسپ انداز تحریر سے اس ناول میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تارڑ نے اپنے اس ناول میں ’’سلطانہ شاہ‘‘ کے حوالے سے عالمی سطح پر بننے والے نئے تہذیبی منظر کو قدیم تہذیب کے کھنڈرات سے ملا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گزرتی صدیوں نے انسانی صورتحال میں کوئی بہتری پیدا نہیں کی۔ سلطانہ شاہ ایک ایرانی مسلمان فرد کی بات سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کی طرف لوٹ آتی ہے لیکن خاور ایک بار پھر اسے جنسی مہمات کی طرف لے جاتا ہے جس سے انسان کی بے چارگی کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ ناول کے آخر تک آتے آتے خاور مکمل شکست اور انہدام کی علامت بن جاتا ہے اور موت اس کی شکست پر آخری مہر لگا دیتی ہے۔
مستنصر حسین تارڑ کا جو تخلیقی سفر ’’بہاؤ‘‘ سے شروع ہوا تھا وہ ’’راکھ‘‘ سے ہوتے ہوئے ایک حد تک ’’قربت مرگ میں محبت‘‘ پر ختم ہوتا ہے۔ تارڑ نے اپنے اس تخلیقی سفر میں یقینا اردو ناول میں بہت اہم تجربے کیے ہیں۔ خاص طور پر ’’بہاؤ‘‘ کو ہم یقینا اردو ناول کی تاریخ میں نہایت اہم اضافہ قرار دے سکتے ہیں۔ راکھ اپنے نفسِ مضمون کے اعتبار سے اور معاصر تاریخ کو فنکارانہ فاصلے سے دیکھنے کے اعتبار سے اچھی کوشش تھی لیکن ’’قربت مرگ میں محبت‘‘ اپنی بعض خوبیوں کے باوجود اتنا کامیاب تجربہ نہیں جتنے پہلے کے دونوں ناول تھے۔
اوپر ہم نے مستنصر حسین تارڑ کے ان ناولوں پر نگاہ ڈالی ہے جو بیسویں صدی میں شایع ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اکیسویں صدی کے ساتھ ان کے ہاں ایک نئی تخلیقی انگیخت آئی ہے اور انھوں نے تواتر سے بہت اچھے ناول تحریر کیے ہیں۔ ’’قلعہ جنگی‘‘، ’’ڈاکیا اور جولاہا‘‘، ’’خس و خاشاک زمانے‘‘، ’’منطق الطیر جدید‘‘ اور اب ’’شہر خالی… کوچہ خالی‘‘ ایسا لگتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے تخلیقی وفور میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے باطن میں موجود تمام تجربات کو صفحات پر منتقل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔
’’قلعہ جنگی‘‘ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد فوری تخلیقی اظہار کے طور پر سامنے آیا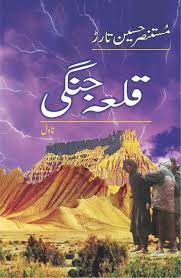 اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خوبصورت اظہار تھا۔ افغانستان پر حملہ کے بعد قلعہ جنگی میں افغانستان کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک رونما ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ وحشت اور بربریت کا اظہار کرنے والے ’’دہشت گرد افغان طالبان‘‘ نہیں تھے بلکہ مہذب اور انسانیت پسند امریکہ تھا۔ افسوس ہمارے ہاں انسانیت کے علمبرداروں نے اس واقعہ سے صرفِ نظر کیا لیکن تارڑ نے اس واقعہ پر ایک ناول لکھ کر اسے ادب میں محفوظ کر دیا۔ ’’قلعہ جنگی‘‘ میں سینکڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ ہتھیار پھینک چکے تھے مگر انھیں بے دردی سے مارا گیا۔ مستنصر حسین تارڑ نے اس واقعہ کے سیاسی پہلوؤں کو زیر بحث لانے کی بجائے اسے ایک انسانی المیے کے طور پر دیکھا ہے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خوبصورت اظہار تھا۔ افغانستان پر حملہ کے بعد قلعہ جنگی میں افغانستان کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک رونما ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ وحشت اور بربریت کا اظہار کرنے والے ’’دہشت گرد افغان طالبان‘‘ نہیں تھے بلکہ مہذب اور انسانیت پسند امریکہ تھا۔ افسوس ہمارے ہاں انسانیت کے علمبرداروں نے اس واقعہ سے صرفِ نظر کیا لیکن تارڑ نے اس واقعہ پر ایک ناول لکھ کر اسے ادب میں محفوظ کر دیا۔ ’’قلعہ جنگی‘‘ میں سینکڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ ہتھیار پھینک چکے تھے مگر انھیں بے دردی سے مارا گیا۔ مستنصر حسین تارڑ نے اس واقعہ کے سیاسی پہلوؤں کو زیر بحث لانے کی بجائے اسے ایک انسانی المیے کے طور پر دیکھا ہے۔
’’قلعہ جنگی‘‘ زندگی کی آس میں جیتے مرتے کرداروں کی کہانی ہے۔ وہ آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں مگر اپنی زندگی کی بقا کے لیے خود غرض بھی ہیں۔ تباہی اور بربادی کے مناظر میں انسانی نفسیات کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ ’’قلعہ جنگی‘‘ میں اس کی تخلیقی عکاسی کی گئی ہے۔
’’اس لیے کہ میں بھی۔۔۔ نہیں نہیں۔۔۔ ہوں۔۔۔ آہو۔۔۔ بیگ جی میں نے تم سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ گھوڑے کو کھایا۔۔۔ آسانی سے گھوڑا میں نے اس لیے کھایا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بھوکا ہوں۔ تم سب اجے بچے لوگ ہو کھاتے پیتے گھروں کے۔۔۔ تم تو صرف پچھلے چار پانچ دن سے بھوکے ہو اور میں ہمیشہ سے بھوکا ہوں اس لیے میں نے گھوڑا آسانی سے کھایا ہے آہو۔۔۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ بخش اگر تم ہو تو کیوں ہو کیوں کہ میں کمی کمین ہوں۔۔۔ اور تم نے بھی نہیں پوچھا بیگ بھائی۔۔۔‘‘ (قلعہ جنگی، ۲۰۰۸ء، ص؛۱۰۰)
ناول کی ابتدا ایک مختصر سے مکالمے سے ہوتی ہے۔ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سات زخمی افغان بھوک اور خوف کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انھوں نے ’’قلعہ جنگی‘‘ کے ایک تہہ خانہ میں پناہ لے رکھی ہے اور بیرونی دنیا سے ان کے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ قلعہ میں ہر طرف موت کی ویرانی ہے۔ لاشوں سے اٹھنے والا تعفن اور کسی بھی لمحے کسی سمت سے آنے والی گولی کا خوف، ہر وقت اعصاب کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ یہ سات کردار اپنے اپنے طور پر بھوک اور موت کے خوف سے لڑ رہے ہیں۔ ایسی ہی صورت حال قدرے مختلف انداز میں ہمیں ’’بہاؤ‘‘ کے آخر میں دکھائی دی تھی۔ جب دریا کے خشک ہونے سے اجڑتی بستی کے کردار خوفناک بھوک کے سامنے تھے۔ تارڑ اپنے ناولوں میں دو بنیادی جبلتوں بھوک اور جنس کی طرف بار بار پلٹتے ہیں اور انسانی کردار پر ان جبلتوں کے اثرات کا تخلیقی اظہار کرتے ہیں۔
’’قلعہ جنگی‘‘ اپنے اختصار کے باوجود ایک المیہ تخلیقی تجربہ ہے۔ اس ناول کے سات کردار دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ناول نگار نے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ان کرداروں کے تہذیبی پس منظر کو بڑی خوبی سے ابھارہ اور اسے اپنے ناول میں بیانیے کی تشکیل میں برتا ہے۔ عصری تاریخ کے اعتبار سے ’’قلعہ جنگی‘‘ اس وقت تخلیق کیا گیا جب امریکی استعمار اپنی پوری طاقت میں تھا اور یہ منہ زور عفریت ساری دنیا کو ہڑپ کر لینا چاہتا تھا۔ اب بیس سال بعد جب امریکہ اپنی تاریخی کی بدترین شکست کھا کر اس خطے سے نکل چکا ہے۔ اس کی بے پناہ طاقت اور ٹیکنالوجی اسے فتح نہیں دلا سکی تو اس کے طیاروں کے پروں سے لپٹ کر افغانستان سے باہر جانے والے لوگوں کی داستان بھی کسی کو لکھنی ہے کہ امریکی استعمار کا ساتھ دینے کے باوجود ان کی حیثیت امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے کتوں سے بھی کم نکلی۔ شاید یہ کہانی بھی مستنصر حسین تارڑ ہی لکھے گا۔
مستنصر حسین تارڑ کا اگلہ پڑاؤ ’’ڈاکیا اور جولاہا‘‘ کی شکل میں سامنے آیا جو بنیادی طور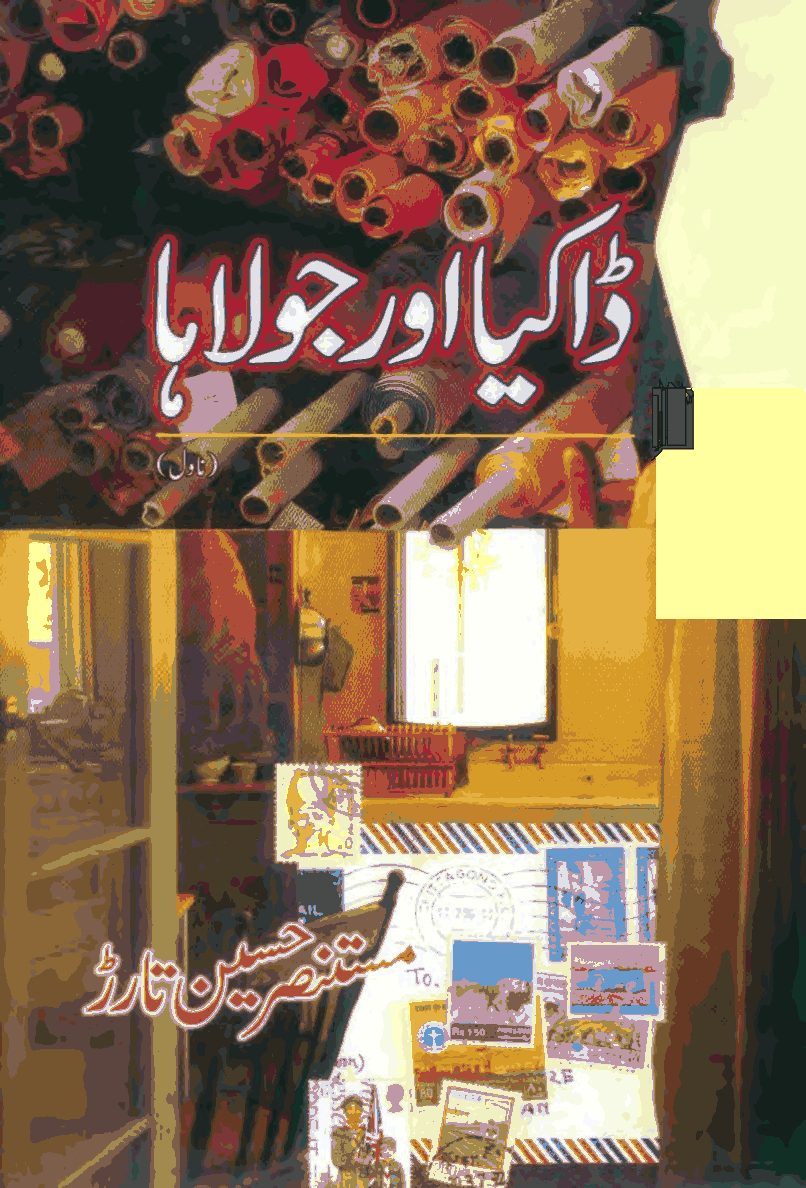 پر علامتی اور استعاراتی امنگ کا ناول ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کے دو کرداروں ’’ڈاکیا‘‘ اور ’’جولاہا‘‘ پس منظر دیہی ماحول کا ہے کہ ڈاکیا اور جولاہا، دیہی زندگی کے اہم کردار ہیں۔ ڈاکیا پیغام رسانی کا ذریعہ ہے اور جولاہا کھڈی پر دھاگے کے تاروں کو تانے بانے کی مدد سے کپڑے میں تبدیل کرنے والا ہنر مند۔ اس ناول میں ایسا لگتا ہے کہ جولاہا کپڑا نہیں بن رہا انسانی زندگی کے تار و پود تیار کر رہا ہے اور ڈاکیا، انسان پر زندگی اور کائنات کے راز فاش کر رہا ہے۔
پر علامتی اور استعاراتی امنگ کا ناول ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کے دو کرداروں ’’ڈاکیا‘‘ اور ’’جولاہا‘‘ پس منظر دیہی ماحول کا ہے کہ ڈاکیا اور جولاہا، دیہی زندگی کے اہم کردار ہیں۔ ڈاکیا پیغام رسانی کا ذریعہ ہے اور جولاہا کھڈی پر دھاگے کے تاروں کو تانے بانے کی مدد سے کپڑے میں تبدیل کرنے والا ہنر مند۔ اس ناول میں ایسا لگتا ہے کہ جولاہا کپڑا نہیں بن رہا انسانی زندگی کے تار و پود تیار کر رہا ہے اور ڈاکیا، انسان پر زندگی اور کائنات کے راز فاش کر رہا ہے۔
دیہی معاشرت، مستنصر حسین تارڑ کے اہم تخلیقی سوتوں میں سے ایک ہے۔ ڈاکیا اور جولاہا میں یہی دہی معاشرت اور اس میں رچے بسے کردار، ایک خاص ڈھنگ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں ناول میں دیہی زندگی کا بیان ہے وہاں ناول نگار نے سماں باندھ دیا ہے۔ خاص طور پر اس ناول میں قوالی کا منظر اور اس منظر سے وابستہ حالات و واقعات کا بیان نہایت عمدہ ہے۔ نورے ماچھی اور دینے تیلی کے برنے سے لٹکتے ہوئے کردار قوال کے بول سے بے حال ہوتے، حال کھیلتے حال سے بے خبر، کہیں دور زندگی کرتے، ایک مسحور کن منظر تشکیل دیتے ہیں۔ ڈاکیا اور جولاہا کا تہہ دار بیانیہ اپنے اندر اسرار کی کیفیت لیے ہے۔ معلوم سے نا معلوم کی طرف، مادیت سے غیر مادیت کی طرف جسم سے روح کی طرف ناول کے مناظر ہمیں ایک اور عالم میں لے جاتے ہیں۔
’’بدخشانی گھوڑے پر سوار وہ شاید صرف ایک رو دین کی تلاش میں ادھر آ نکلا تھا۔ اس کے چرمی تھیلے میں پچیس برس پیشتر لکھا گیا کوئی ایسا خط ہو سکتا تھا جو نتالیہ نے اپنے سرخ عروسی جھوڑے کی کسی اندرونی کروٹ میں اس نیت سے سنبھالا ہو کہ وہ موقع ملنے پر اپنے خاوند سے پوشیدہ ہو کر اسے پوسٹ کر دے گی اور وہ نہ کر سکی۔۔۔ شاید بھول گئی۔۔۔ شاید مر گئی اور اس کے سیاہ رومی صندق کی تہہ میں سے برآمد ہونے والے۔۔۔ اب تک بوسیدہ ہو چکے کہ اس کے تار ڈھیلے اور مردہ ہو چکے ہوں عروسی جوڑے کی اندرونی کروٹ میں سے کسی کے ہاتھ نے۔۔۔ شاید اس کی بیٹی کے جستجو کرتے ہاتھ نے اسے وہاں پایا اور پوسٹ کر دیا ہو۔۔۔ شاید! شاید اس خط میں بالآخر اس نے ہار مان لی ہو اور اقرار کیا ہو کہ ایک سید زادی پر آیا ہوا جن اتر گیا ہے۔۔۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر ایک نئی اور سنہری کرنوں کے گوتے سے آراستہ زندگی میں آزادی اور چھٹکارے کے ایک نئے احساس کے ساتھ داخل ہو رہی ہے۔ وہ جولاہی نہیں رہی۔
’’برنے کے پیڑ سے بندھے رسے کو اس نے اپنے پاؤں سے کھول کر خود کو آزاد کر لیا ہے۔۔۔ عشق کی پینگ کے ہلارے سے نجات حاصل کر لی ہے اور وہ اب صرف غم حسین میں روتی ہے۔‘‘ (’’ڈاکیا اور جولاہا‘‘، ۲۰۰۵ء، ص:۱۸۷۔۱۸۶)
مستنصر حسین تارڑ نے ناولوں میں بعض حیرت انگریز شہابتیں ملتی ہیں۔ مثلاً ’’قربت مرگ میں محبت‘‘ کا خاور اور رودین، یا بہاؤ کی پاروشنی اور قربت مرگ میں محبت ‘‘ کی پکھی ہمیں ایک دوسرے کے ہمزاد محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی اور کردار مثلاً ’’پیار کا پہلا شہر‘‘ کی پاسکل کئی شکلیں بدلنے کے بعد ان کے بعد کے ناولوں میں موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تارڑ کے ہر ناول کے تاروپود اس کے دوسرے ناولوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ’’ڈاکیا اور جولاہا‘‘ کے اندر سے ہمیں مستنصر حسین تارڑ کا ایک اور نہایت اہم ناول ’’خس و خاشاک زمانے‘‘ اپنی شکل بناتا دکھائی دیتا ہے۔
’’خس و خاشاک زمانے‘‘ (۲۰۱۰ء) ہمیں مستنصر حسین تارڑ کے فن میں ایک اہم تخلیقیت کے طور پر ملتا ہے اور اس ناول کا زمانی اور مکانی دائرہ کافی وسیع ہے۔ یہ ناول ۱۹۲۰ء کی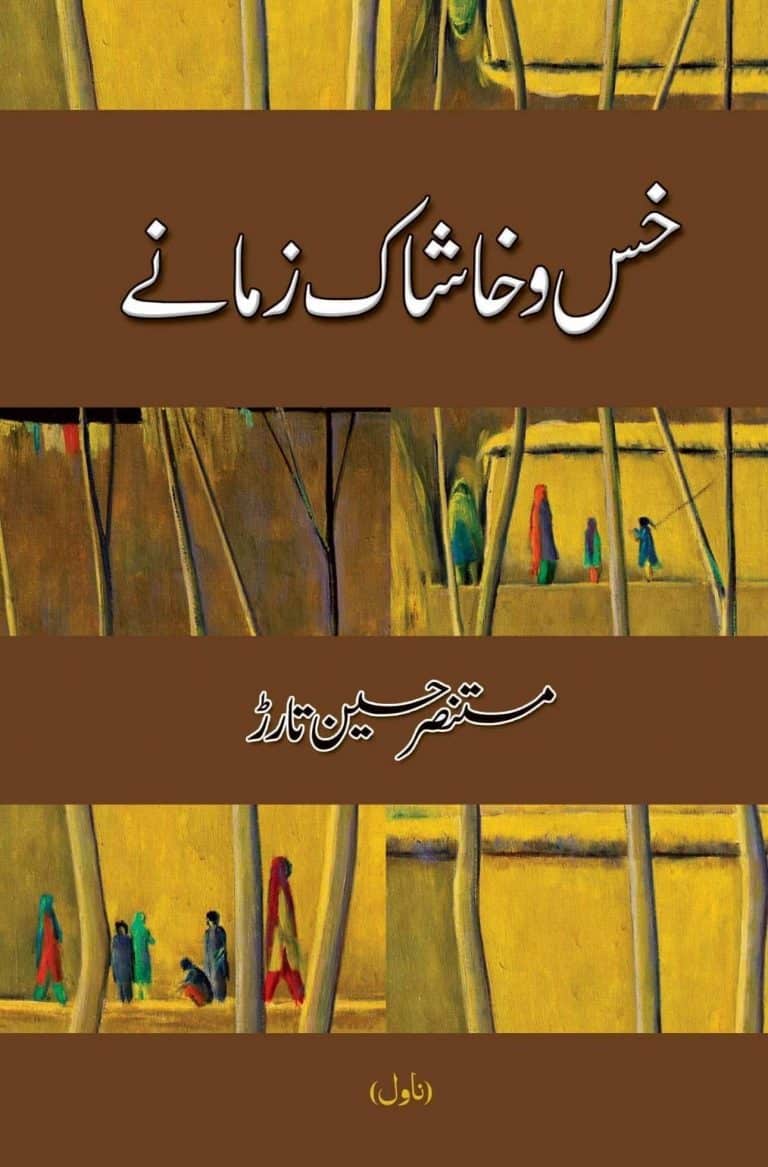 دہائی سے شروع ہو کر اکیسویں صدی کی ابتداء تک آتا ہے اور مکانی سطح پر گجرات کے دیہات سے شروع ہو کر لاہور جیسے تہذیبی مرکز سے ہوتا نئی دنیا امریکہ کی سر زمین پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس ناول میں واقعات کا تیز بہاؤ انسان کو بے بس تنکے کی طرح بہائے لیے جا رہا ہے۔ انسانی کردار تاریخی واقعات کے سامنے بے بس ہیں۔ گجرات، لاہور، نیویارک، کینیڈا، افغانستان اور عراق، طرح طرح کے خطے ناول میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ ۷۰،۸۰ سال کے زمانی وقفے اور وسیع جغرافیے خطے کو محیط یہ ناول تین نسلوں کے افراد کی روداد بن جاتا ہے جو اپنے اپنے مقدر کا لکھا کاٹ رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن وقت بار بار انھیں ایسی صورت حال سے دو چار کر دیتا ہے جس کی نہ انھیں خواہش ہے نہ ضرورت۔
دہائی سے شروع ہو کر اکیسویں صدی کی ابتداء تک آتا ہے اور مکانی سطح پر گجرات کے دیہات سے شروع ہو کر لاہور جیسے تہذیبی مرکز سے ہوتا نئی دنیا امریکہ کی سر زمین پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس ناول میں واقعات کا تیز بہاؤ انسان کو بے بس تنکے کی طرح بہائے لیے جا رہا ہے۔ انسانی کردار تاریخی واقعات کے سامنے بے بس ہیں۔ گجرات، لاہور، نیویارک، کینیڈا، افغانستان اور عراق، طرح طرح کے خطے ناول میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ ۷۰،۸۰ سال کے زمانی وقفے اور وسیع جغرافیے خطے کو محیط یہ ناول تین نسلوں کے افراد کی روداد بن جاتا ہے جو اپنے اپنے مقدر کا لکھا کاٹ رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن وقت بار بار انھیں ایسی صورت حال سے دو چار کر دیتا ہے جس کی نہ انھیں خواہش ہے نہ ضرورت۔
’’خس و خاشاک زمانے‘‘ میں انسانی کرداروں کا ایک جنگل آباد ہے۔ مرد کردار اپنی اپنی مخصوص نسلی و نفسیاتی کیفیات کے ساتھ اپنی جھلک دکھاتے ہیں جیسے سرور سانسی، لہنان سنگھ، بخت جہان، محمد جہاں، امیر بخش، سوہن سنگھ، اچھو شیخ وغیرہ اور یہ کردار ہمیں مشترکہ پنجاب کی دیہی ثقافت کی نمائندگی کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ خاص طور پر دریائے چناب کے اطراف میں پھیلا پنجاب، گجرات، وزیر آباد اور گوجرانوالہ کے دیہات اور ان کی معاشرت کا بیان بہت عمدہ ہے۔ اس معاشرے میں ذات برادری بعض اوقات مذہب سے زیادہ مضبوط تعلق تھا اور سکھ اور مسلمان جاٹ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ محبتیں اور دشمنیاں پروان چڑھتی اور انسان رشتے کو نبھانے میں زندگی ہار دیتے۔ اس ناول میں بخت جہاں اور نہان سنگھ انسانی فطرت میں موجود وحشی پن کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس معاملے میں جو نسوانی کردار ان کا ہم پلہ ہے وہ بلونت کور کا ہے۔ محمد جہاں اور اس کی بیوی شائستگی اور تہذیب کی علامت ہیں۔ جو رفتہ رفتہ وحشت اور بربریت کے سامنے ڈھیر ہو رہی ہے۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقع فتح بخت جہاں کی ہوتی ہے یا آخر میں مردار کھانے تک آ جانے والا بخت جہاں خود اپنی شکست کی آواز بن جاتا ہے اور اس کی بیٹی ’’صاحباں‘‘ مشہور لوک داستانی کردار کی مثل اپنی جسمانی بے ہنگمی کے باوجود جیون کی ایک ایسی سطح پر نظر آتی ہے جہاں انسان کے ظاہری حوالے بے معنی ہو جاتے ہیں۔
’’خس و خاشاک زمانے‘‘ میں مردانہ کرداروں کے ساتھ ساتھ بعض نسوانی کردار بھی اپنی باطنی طاقت کی بدولت قاری کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان نسوانی کرداروں میں صاحباں، مقدس بیگم، نور بیگم، بلونت کور، امرت کور، ماہلو، کنیز فاطمہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ نے ہر کردار کی انفرادیت کو اس کے جسمانی خصائص اور نفسیاتی اوصاف سے نمایاں کیا ہے اور بطور ناول نگار یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ اپنے ناول میں انسانی وجود، معاشرتی صورت اور ان دونوں کے تال میل سے بننے والی کیفیات اور واقعات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔
مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ناول ’’خس و خاشاک زمانے‘‘ میں کرداروں کی فطرت اور نفسیات کا عمدہ مطالعہ کیا ہے۔ یہاں انھوں نے ایک اہم نقطے کو ابھارہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک خود غرض اور اپنی ذات کا اسیر ہے۔ ظاہر ہے یہ انسان کے بارے میں کوئی نیا نقطۂ نظر نہیں ہے بلکہ صدیوں سے فلسفی اور انسانی نفسیات کا مطالعہ کرنے والے بڑے دانش ور اس نوع کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تارڑ نے اپنے ناول میں اس نقطۂ نظر کو فکری سطح پر زیرِ بحث لانے کی بجائے اسے اپنے کرداروں کے عمل اور انسانی صورت حال سے ابھارہ ہے۔ یہاں وہ اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ تہذیب اور مذہب انسان کی بنیادی فطرت میں تبدیلی نہیں لا سکے۔ مثلاً اس کی مثال میں نہاں سنگھ کے بیٹوں کا اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جانا لیکن اپنے نسلی اور خاندانی خصائص پر قائم رہنا ہے یا کچھ ایسا ہی ماجرا ’’بخت جہاں‘‘ کے بیٹے اکبر جہاں کا نظر آتا ہے کہ اپنے باپ سے دور پرورش پانے کے باوجود وہ فطرتاً اپنے باپ کی تصویر بنتا جاتا ہے۔
مستنصر حسین تارڑ نے اپنے اس ناول میں جاٹ اور سانسی نسل کے افراد کے عمدہ کردار تراشے ہیں۔ پنجاب کی سر زمین کے یہ باشندے صدیوں سے ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو زندگی گزارتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ کہیں کہیں ان میں اختلاط بھی ہوتا ہے لیکن نسلی خصوصیات تہذیبی معیارات پر غالب آتی ہیں۔ اس ناول میں نسلی اختلاط سے ایک نئے آدم کے پیدا ہونے کی نوید یا خواہش کا اظہار بھی ملتا ہے۔ ایک ایسا نیا کردار جو پیدائشی طور پر اعلیٰ انسانی خصوصیات کا حامل ہو۔ ناول نگار کی یہ خواہش شاید مستقبل بعید میںپوری ہو کیوں کہ مستقبل قریب میں اس کے امکانات کم ہیں۔ ’’خس و خاشاک زمانے‘‘ کا انتساب بھی ’’عطا کے پرندوں اور نئے آدم کے نام‘‘ ہے۔ جو ایک سطح پر نئے آدم کے ظہور کی خواہش سے جڑا ہے اور دوسری سطح پر ان کے بعد میں آنے والے ناول ’’منطق السطیرجدید‘‘ سے جڑا ہے لیکن ان دو ناولوں کے درمیان ان کا ایک ناول ’’اے غزالِ شب‘‘ پڑتا ہے تو پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔
’’اے غزالِ شب‘‘ شکست آرزو کا بیان ہے۔ وہ لوگ جنھوں نے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں اپنی آنکھوں میں ایک نئی معاشرت اور ایک نئی دنیا کے خواب سجائے۔ ملک سے ہجرت کی۔ اپنی اپنی زندگیوں کے تیس تیس چالیس چالیس سال دیارِ غیر میں بسر کیے اور پھر یکخت وہ سب مٹی کا ڈھیر بن گیا، خواب بکھر گیا۔ نظام ٹوٹ گیا اور اب حسرت ہے تاسف ہے اور واپسی کا سفر ہے۔ مگر یہاں بھی تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اپنے بیگانے بن چکے ہیں۔ جگہیں اور لوگوں کے چہرے مشکل سے پہچانے جاتے ہیں اور ’’اے غزالِ شب‘‘ کے کردار اپنی اپنی کہانی یا بپتا سناتے ہیں اور اس ماضی کو یاد کرتے ہیں جو کبھی کا نابود ہو چکا ہے۔
اپنی اپنی زندگیوں کے تیس تیس چالیس چالیس سال دیارِ غیر میں بسر کیے اور پھر یکخت وہ سب مٹی کا ڈھیر بن گیا، خواب بکھر گیا۔ نظام ٹوٹ گیا اور اب حسرت ہے تاسف ہے اور واپسی کا سفر ہے۔ مگر یہاں بھی تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اپنے بیگانے بن چکے ہیں۔ جگہیں اور لوگوں کے چہرے مشکل سے پہچانے جاتے ہیں اور ’’اے غزالِ شب‘‘ کے کردار اپنی اپنی کہانی یا بپتا سناتے ہیں اور اس ماضی کو یاد کرتے ہیں جو کبھی کا نابود ہو چکا ہے۔
مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ناول کا عنوان ن۔ م راشد کی ایک نظم سے مستعار لیا ہے۔ یہ نظر ’’لا: انسان‘‘ میں شامل ہے اور اس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔
’’اے غزالِ شب
تیری پیاس کیسے بجھاؤں میں
کہ دکھاوں میں وہ سراب جو مری جاں میں ہے
وہ سراب ساحرِ خوف ہے
وہ سحر سے شام کے رہگذر میں فریبِ زہر وسادہ ہے
وہ سراب سادہ، سراب گر، کہ ہزار صورتِ نو بنو میں قدم قدم پہ ستارہ ہے
وہ جو غالب و ہمہ گیر ودشتِ گماں میں ہے
مرے دل میں جیسے یقین بن کے سما گیا ہے
مرے ہست و بود پہ چھا گیا‘‘
’’اے غزالِ شب‘‘ چار کرداروں یا در ویشوں کی کہانی ہے۔ یہ درویش ظہیر الدین، مظہر السلام، سردار قالب اور عارف نقوی ہیں۔ اپنے نظریے، اپنے خواب کا تعاقب کرتے یہ کردار دور دیسوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ ان پر جب یہ واضع ہوتا ہے کہ جس خواب کا وہ پیچھے زندگی بھر دوڑتے رہے ہیں وہ حقیقت میں بالکل بدل چکا ہے تو شدید بے چینی اور بے بسی ان کرداروں پر طاری ہوتی ہے۔ انھیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ گھر کے رہے ہیں اور نا گھاٹ کے، تب انھیں خواب دکھانے والے ترقی پسند شاعر اور ادیب اپنے اصل دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ اشتراکیت کے نظام نے انسانی زندگی کو بدلنے کا ایک خواب دکھایا تھا۔ انسان وجود میں مساوات اور برابری کی آرزو کو ایک مجسم شکل دی تھی۔ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد دیگر مشرقی یورپ سوشلسٹ ممالک اپنے نظام کو بدلتے چلے گئے اور اب آزاد مندی اور لبرل جمہوریت کا عفریت ان کے سامنے تھا جس سے بچ کر وہ برسوں پہلے اپنے ملک سے نکلے تھے خو کو اس کے مقابل دیکھ کر ان کے پرانے ڈر جاگ جاتے ہیں وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں اپنے وطن کی جانب معراجیت کرتے ہیں۔ جہاں اب بہت کچھ بدل چکا ہے اور بدلی ہوئی صورت حال میں وہ اپنے ملک میں بھی اجنبی ہیں۔ یہ وہ المیاتی صورت حال ہے جس نے مستنصر حسین تارڑ کے اس ناول ’’اے غزال شب‘‘ کو ایک قابل قدر تخلیقی تجربے میں تبدیل کر دیا ہے۔
مستنصر حسین تارڑ کے ناول ’’اے غزالِ شب‘‘ کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اسے سوشلزم مخالف ناول کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی اور اسے ہدف تنقید بنایا۔ یاد رہے کہ ناول نگار اپنی ابتدا ہی سے ترقی پسند فکر کا حامل رہا ہے۔ اس ناول میں بھی ہمیں کسی نظریے کی حمایت نہیں ملتی۔ ناول نگار نے انسانی کرداروں میں ہونے والی اس شکست و ریخت کو پیش کیا ہے جو نظریاتی انہدام کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس نے بیرون ملک آباد کرداروں کا انتخاب اسی احتیاط کے پیش نظر کیا تھا ورنہ وہ اپنے اردگرد بسنے والے ان کرداروں کا انتخاب بھی کر سکتا تھا جو سوویت یونین کے باقی رہنے تک سوشلسٹ تھے مگر سوویت یونین کے انہدام کے فوراً بعد سیکولر لبرلر ہو گئے۔ جمہوریت اور آزادی معیشت کی حمایت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی۔ وہ شہر کی چھوٹی چھوٹی بستیوں اور گوالمنڈی، نسبت روڈ سے اٹھ کر ڈیفنس میں آباد ہو گئے۔ دراصل مستنصر حسین تارڑ اس بات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ کیا انسان کا حالات کے ساتھ خود کو بدلتے چلے جانا کامیابی ہے یا اپنی نظریاتی اور فکری اساس کے ساتھ زندہ رہنا اصل کامیابی ہے۔
عطار کے پرندوں سے ہمارا تعارف تو ’’خس و خاشاک زمانے‘‘ کے انتساب میں ہو گیا تھا مگر ناول ’’منطق الطیر، جدید‘‘، ’’اے غزال شب‘‘ کے بعد منظرِ عام پر آیا۔ یہ ناول ایک مختلف جہت سے انسانی زندگی اور خارجی حقیقت کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ اس ناول کا انتساب ’’پرندوں کی بولیاں میرے کانوں میں پھونکنے والے ’’مرشد عطار کے نام‘‘ ہے اور یہاں ٹِلہ جوگیاں ہیں۔ مختلف اطراف سے آتے پرندے ہیں جو مختلف مذاہب اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ سب انسان کے روحانی سفر کے استعارے ہیں مادیت سے بلند ہو کر چیزوں کو دیکھنے کی خواہش ہے اور وہ سب کچھ پانے کی خواہش جو انسان حاصل نہیں کر سکا اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بھی دولت مند، طاقتور اور دانا ہو جائے۔ زندگی کے گلاس کا ایک حصہ ہمیشہ خالی رہتا ہے اور یہ خالی حصہ ہے جو انسان کو نئے جہانوں اور نئے قرنوں کی مسافت پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان اپنے زندگی بھر کے تصورات کو پس پشت ڈال کر وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جسے وہ دقیانوسی جہالت سے تعبیر کرتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو ناول نگار نے اپنے زیر نظر ناول میں فکشن کی شکل میں پیش کیا ہے۔
جہت سے انسانی زندگی اور خارجی حقیقت کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ اس ناول کا انتساب ’’پرندوں کی بولیاں میرے کانوں میں پھونکنے والے ’’مرشد عطار کے نام‘‘ ہے اور یہاں ٹِلہ جوگیاں ہیں۔ مختلف اطراف سے آتے پرندے ہیں جو مختلف مذاہب اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ سب انسان کے روحانی سفر کے استعارے ہیں مادیت سے بلند ہو کر چیزوں کو دیکھنے کی خواہش ہے اور وہ سب کچھ پانے کی خواہش جو انسان حاصل نہیں کر سکا اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بھی دولت مند، طاقتور اور دانا ہو جائے۔ زندگی کے گلاس کا ایک حصہ ہمیشہ خالی رہتا ہے اور یہ خالی حصہ ہے جو انسان کو نئے جہانوں اور نئے قرنوں کی مسافت پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان اپنے زندگی بھر کے تصورات کو پس پشت ڈال کر وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جسے وہ دقیانوسی جہالت سے تعبیر کرتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو ناول نگار نے اپنے زیر نظر ناول میں فکشن کی شکل میں پیش کیا ہے۔
’’منطق الطیر، جدید‘‘ کا آغاز ہمیں تارڑ کے ناولوں ’’راکھ‘‘ اور ’’قربت مرگ میں محبت‘‘ کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح کی جو شباہتیں وہ اپنے ناولوں میں شعوری طور پر پیدا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں غیر ضروری ہیں۔ ناول کے خارج میں موجود اشتراکات سے زیادہ ناول کے باطن میں موجود اشتراکات قاری کو متاثر کرتے ہیں کیوںکہ انھیں قاری خود دریافت کرتا ہے اور اس وقت قاری کو جو انبساط حاصل ہوتی ہے اس کا تصور محال ہے۔ مگر شاید تارڑ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے قارئین کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ اسے گمان ہوتا ہے کہ شاید سب قاری ناولوں کے باطن میں موجود مماثلتوں تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ اس لیے وہ اپنے ناول میں قاری کے لیے سہولت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔
’’منطق الطیر، جدید‘‘ کے بیانیے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں۔ مختلف تہذیبوں اور خطوں سے تعلق رکھنے والی کہانیاں، جو پرندے اپنے ساتھ لائے ہیں اور ٹِلہ جوگیاں پر سناتے ہیں۔ ایسے میں ایک جدید کہانی ’’موسیٰ حسین‘‘ اور ’’صفورہ‘‘ کی ہے جو جدید تعلیم سے آراستہ، پر آسائش زندگی بسر کرتے آرٹسٹ ہیں۔ انھیں زندگی میں سب کچھ میسر ہے مگر اولاد سے محرومی انھیں دکھ دیتی ہے ان کی زندگی میں تلخی گھولتی ہے اور انھیں نا آسودہ بناتی ہے اور یہی ناآسودگی ہے جو موسیٰ حسین کو ایک ایسے سفر پر آمادہ کرتی ہے جو اس پر زندگی کے نئے معنی آشکار کرتا ہے۔
’’منطق الطیر، جدید‘‘ میں مستنصر حسین تارڑ نے کئی ایک نازک سوال اٹھائے ہیں لیکن اس سلیقے سے کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اصل میں فکشن نگار کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ فکشن کے لبادے میں حقیقت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ بات قاری تک پہنچ بھی جاتی ہے اور لکھنے اور پڑھنے والے دونوں کا بھرم بھی رہ جاتا ہے۔
’’سچ نیا یا پرانا نہیں ہوتا البتہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔۔۔ وہ جو آسمانی احکام تھے کب کے طاقچوں میں دھرے تھے ان پر کائی نمودار ہو رہی تھی۔۔۔ بدھ کے مجسمے شکست و ریخت کا شکار ہو رہے تھے۔۔۔ کوہ طور کی آگ سرد ہو گئی تھی۔۔۔ وہ بڑھی جس صلیب پر نصیب کر دیا گیا تھا اس کی لکڑی کو گھن لگ گئی تھی اور کوئی بھی ’’اقراء‘‘ کی صدا پر دھیان نہ کرتا تھا جیسے سلیمان رخصت ہوئے تو کسی کو خبر نہ ہوئی اور جب جس عصا سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اسے گھن کھا گئی اور وہ مسمار ہوا تب سلیمان کی رخصتی کی خبر ہوئی۔۔۔ کرشن کی بانسری چپ ہو چکی تھی تو ان مجسموں کو پھر سے قابل پرستش بنانے کے لیے اس سرد ہو چکی جھاڑی کو پھر سے سلگانے کی خاطر، اس صلیب کو پھر سے ایستادہ کرنے کے لیے، اس بانسری کی دھنوں کو پھر سے بیدار کرنے کے لیے اور اقرا کی صدا کو دوبارہ کل جہانوں میں گونجنے کے لیے ہم سب عطار کے پرندے ہو گئے۔۔۔ ہم نے ایک لائی لگ مومن کی بجائے کھوجی کافر ہونا پسند کر لیا ہے۔‘‘ (منطق الطیر، جدید‘‘، ۲۰۱۸ء، ص:۱۱۱)
مستنصر حسین تارڑ کے ناول ’’منطق الطیر، جدید‘‘ کا مندرجہ بالا اقتباس ناول کے مرکزی موضوع تک ہماری رسائی کرواتا ہے۔ اگر ناول کی درجہ بندی کرنا مقصود ہو تو اسے ہم موضوعاتی اور فکری ناول قرار دے سکتے ہیں جس میں موجود چند کردار موضوع اور فکر کو نمایاں کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ایک طویل زمانی اور مکانی دائرہ ہمارے سامنے ہے۔ ناول نگار نے نہایت اختصار کے ساتھ اس تصویر کو مکمل کیا ہے جس کے لیے اناڑی لکھنے والا سینکڑوں صفحے ضائع کر دیتا اور پھر بھی کامیاب نہ ہوتا۔
اب آتے ہیں ہم مستنصر حسین تارڑ کے تا حال آخری ناول ’’شہر خالی کوچہ حالی‘‘ کی جانب۔ گزشتہ ڈھیر دو سالوں سے ساری دنیا ایک عالمی وبا کی زد میں ہے۔ ’’کورونا وبا‘‘ جو چین سے شروع ہوئی اور جس نے اب تک دنیا کے کونے کونے میں تباہی مچائی ہے لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کڑوروں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے پاس اپنے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ طرح طرح کی کہانیاں اور نظریے ہیں لیکن ناول نگار کو ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے تو اپنے شہر اور اپنے کردار ’’میں‘‘ کی کہانی سنانی ہے۔ میں جو ہر ہجوم اور ہنستے بستے شہرکارہائشی ہے۔ اب زندگی کی آخری منزل پر ہے اور اس کے سامنے ایک شہر ویران ہے جس سے وہ آشنا ہے بھی اور نہیں بھی۔
سے شروع ہوئی اور جس نے اب تک دنیا کے کونے کونے میں تباہی مچائی ہے لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کڑوروں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے پاس اپنے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ طرح طرح کی کہانیاں اور نظریے ہیں لیکن ناول نگار کو ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے تو اپنے شہر اور اپنے کردار ’’میں‘‘ کی کہانی سنانی ہے۔ میں جو ہر ہجوم اور ہنستے بستے شہرکارہائشی ہے۔ اب زندگی کی آخری منزل پر ہے اور اس کے سامنے ایک شہر ویران ہے جس سے وہ آشنا ہے بھی اور نہیں بھی۔
کورونا وبا کے شب و روز میں انسان بڑے پیمانے پر دو جذبات کا شکار ہوا ہے۔ ’’شک‘‘ اور ’’خوف‘‘۔ اس وبا نے انسانی تعلقات میں رخنا ڈالا ہے۔ میل ملاقات کی نوعیت کو بدل دیا ہے اور آنے والے برسوں میں زندگی کے چلن میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہے۔ اس وبائی صورت حال میں خطرات بھی موجود تھے اور امکانات بھی۔ کروڑوں لوگ خطرات سے ڈر گئے اور چند نے امکانات سے فائدہ اٹھایا۔ مگر زیر نظر ناول کا کردار ’’میں‘‘ نہ خطرات سے ڈرتا ہے کہ زندگی میں خطرے اور ڈر کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے اور نہ اُسے امکانات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ تو بس بدلے ہوئے حالات میں باقی ماندہ زندگی کے دن کاٹنا چاہتا ہے۔ اپنے بیٹے، بہو، پوتے، پوتی کے ساتھ خوشی کے چند لمحات مذید بسر کرنا چاہتا ہے۔ یہی آرزو ’’میں‘‘ کے کردار کو زندگی سے جوڑے ہے وگرنہ اس کے اردگرد تو سب خالی اور ویران ہو چکا ہے اوراس میں میں سب سے زیادہ خود کو تلاش کر رہا ہے جو برسوں کی دھند میں کھو چکا ہے۔ ہنگامی صورت حال پر لکھا گیا ہنگامی نوعیت کا ناول پڑھنے میں دلچسپ ہے۔
مستنصر حسین تارڑ کی ناول نگاری پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انھوں نے اپنے تخلیقی سفر کے دوران چند نہایت غیر معمولی اور اہم ناول لکھے ہیں۔ انھوں نے اپنے ناولوں میں زبان و بیان اور اسلوب کی انفرادیت بھی پیدا کی ہے اور کئی طاقتور، کردار بھی تراشے ہیں۔ انھوں نے متنوع زمانی اور مکانی دائروں میں انسانی کرداروں کی نفسیاتی اور نسلی خصوصیات کو بھی پرکھا ہے اور بعض نہایت نازک موضوعات اور سوالات پر قلم بھی اٹھایا ہے۔ ان سب باتوں کے پیشِ نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تارڑ ہمارے عہد کے سب اہم ناول نگار ہیں۔ انھوں نے اپنے تخلیقی سفر میں نہایت اہم سنگ میل عبور کیے ہیں، شہرت عام حاصل کی ہے اور امید ہے کہ انھیں اردو ادب میں بقائے دوام بھی مل ہو جائے گی۔




