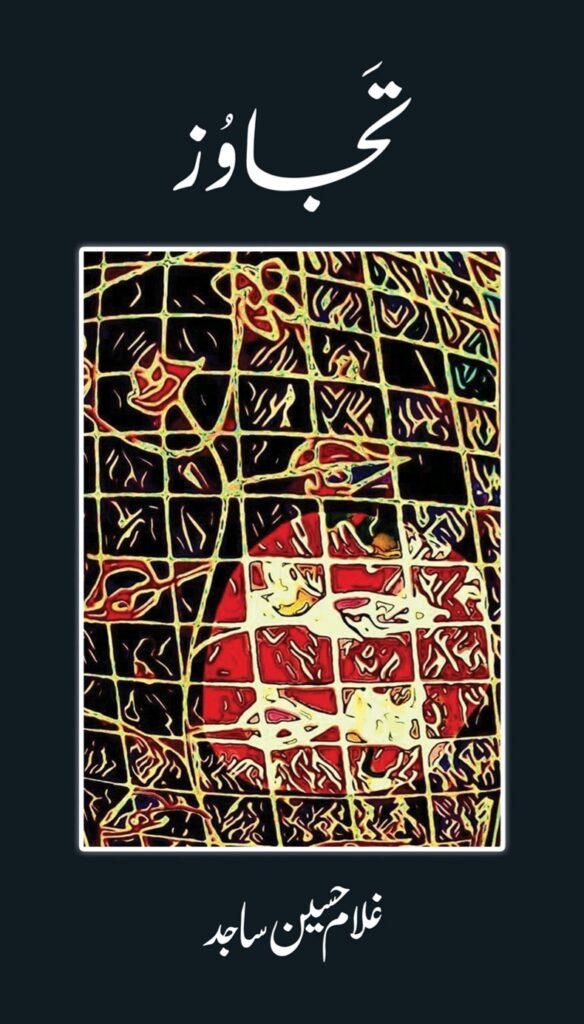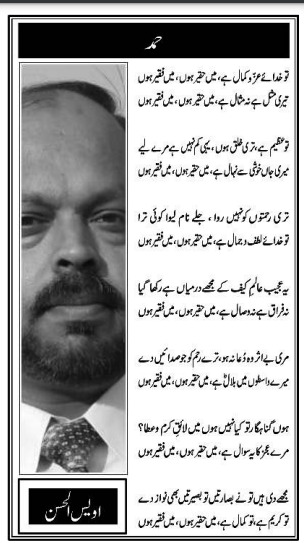نولکھی کوٹھی کا پھوہڑ معمار
اردو میں ناول کی صنف کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے۔ مدرسین اپنے موٹے شیشوں کی عینک کے عقب سے اپنے کوڑھ مغز طلباء و طالبات پر نظرِ شفقت فرماتے ہوئے کرم خوردہ نوٹسز سے یوں سنہری الفاظ لکھواتے ہیں:’’پیارے بچو! ناول افسانوی ادب کی بہت معروف صنف ہے جس میں زندگی کے حقیقی واقعات کا عکس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی اصل میںافسانے سے ہی مماثل ہے۔ دونوں میں صرف طوالت کا فرق ہے۔ افسانہ کی طوالت 3سے دس صفحات ہو سکتی ہے اور ناول 200صفحات سے بھی زیادہ پر محیط ہوتا ہے۔ افسانے میں جن جزئیات سے صرفِ نظر کیا ہے ، ناول میں انھیں پوری تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔افسانے میں زندگی کے ایک پہلو کا اور ناول میں پوری زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ افسانہ زندگی کی ایک قاش ہوتا ہے اور ناول پوری زندگی ہوتا ہے۔‘‘
گزشتہ ستر سال سے یہ تعریف اس قدر راسخ ہو چکی ہے کہ اب ہمارا ناول نگار بھی اس پر ایمان لے آیا ہے۔ ناول نگار یہی سمجھتا ہے کہ افسانے کی کہانی کو دس گنا زیادہ طوالت دے دی جائے تو وہ ناول بن جاتا ہے۔ ہرضروری اور غیر ضروری چیز کی جزئیات لکھ دی، موقع بے موقع ہر جگہ کا منظر تفصیل سے درج کرتے گئے تو ایک عدد معرکۃ الآراء ناول معرضِ وجود میں آ جائے گا۔ ناول کیا ہے، ناول کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا جانیں، بے چارے دو رکعت کے امام۔وہ جو ناول نے اپنے ذمے انسانی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری لی تھی،انسانی شخصیت کے ان پہلوئوں کی دریافت جہاں دنیا کا کوئی مذہب ، کوئی علم نہیں پہنچ سکتا، انسانی شخصیت کی ان گتھیوں کو سلجھانا جو خود انسان کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتیں،نازک جذبات اور خفیف احساسات کی انوکھی تصاویر کو فن کے ذریعے قرطاس پر ابھارنا، یہ سبھی فرائض اردو کے ناول نگار کے حصے میںآئے ہی نہیں۔ بیشتر ناول نگار تو محض کہانی کی طوالت (خواہ جتنی بھی عامیانہ اور گھسی ہوئی ہو) اور جزئیات نگاری (خواہ کتنی غیر ضروری ہو)کو ناول سمجھے بیٹھے ہیں۔ ان کا ملجا و ماویٰ ان دو پہلوئوں سے آگے جاتا ہی نہیں۔وہ جو ناول پر برسوں تک عرق ریزی کی جاتی ہے، وہ ناپید ہے۔ بار بار نظرِ ثانی سے ناول کو حشو و زوائد سے پاک کیا جانا چاہیے، یہ کوئی سوچتا ہی نہیں۔پلاٹ کیا ہوتا ہے، اس کی خوبصورت تعمیر ناول پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ کہا نی میں نیا پن ہی اصل چیز ہوتی ہے، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں۔ کرداروں کواس مہارت سے پیش کیا جانا چاہیے کہ وہ حقیقت سے زیادہ حقیقی محسوس ہوں ، ان کے دکھ سکھ قاری کو اپنے محسوس ہوں اور ان کی اندرونی کیفیات کا علم خود ان سے بھی زیادہ قاری کو ہو،یہ خبر ہی نہیں۔ مکالمے لکھتے وقت کرداروں کے خاندانی پس منظر ، ذاتی طبیعت ، ذہنی رجحان اور علمی حوالہ مدِ نظر رکھنا ہوتا ہے، اس کا علم ہی نہیں ۔حتیٰ کہ ہمارا ناول نگار بیانیے کی بنیادی بُنت سے بھی نابلد ہوتاہے۔ پڑھتے وقت یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کہانی کی زبان ہے یا مضمون کی زبان ہے۔پیراگراف کا پیراگراف اخباری کالم کی طرح گھسیٹ دیا جاتا ہے۔ ناول میں ماحول اورفضا اس طرح پینٹ کرنے ہوتے ہیں کہ ناول کی دنیاصفحات سے ٹھوس شکل میں ابھر کر مجسم نظر آنے لگتی ہے لیکن افسوس یہ اردو کے ناول، آنکھوں میں جن کی نور ، نہ باتوں میں تازگی۔ تِس پر بھی دعویٰ ہوتا ہے، ناول کی تاریخ کا دھارا موڑنے کا۔
تحریر میں عبقریت کا مجھے احساس ہے لیکن حال ہی میںاردو کے دو عدد معرکۃ الآراء ناولوں نے جس قدر بیزار کیا ہے، اس سے مزاج کی تلخی برداشت سے باہر ہو ئی جاتی ہے۔ یہ خیال دل و دماغ کی رگیں نچوڑتا دکھائی دیتا ہے کہ جس زبان میں ڈیڑھ سوسال سے ناول لکھا جا رہا ہو،’’امرائو جان ادا‘‘،’’گئو دان‘‘، ’’آگ کا دریا‘‘، ’’اداس نسلیں‘‘، ’’بستی‘‘، ’’بہائو‘‘، ’’غلام باغ‘‘ اور ’’کئی چاند تھے سرِ آسماں ‘‘ جیسے ناول ظہور پذیرہو چکے ہوں ، وہاں رحمٰن عباس کے ’’روحزن‘‘ اور علی اکبر ناطق کے ’’نولکھی کوٹھی‘‘ جیسے ناولوں کی اس قدر توصیف کی کیا وجہ ہے۔ بونے بونے نقاد اٹھتے ہیں اور کچرا قسم کے ناول کو صدی کا بہترین ناول قرار دے دیتے ہیں اور حیرت ہے کہ بولنے اور سننے والوں کو شرم تک نہیں آتی۔ اس پر ناول نگار بھی ایسے خود پسند ہیں کہ ناول پر محنت کرنے کی بجائے جیسے تیسے ناول چھپوا کر ناقدین کے آستانوں پر جبہ سائی کو چل نکلتے ہیں اور ہزار جبیں فرسائی کے بعد تعریف و توصیف کے
چند چمکتے سکے کاسۂ گدائی میں پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ عبداللہ حسین اور پریم چند جیسی لگن اور فنکاری تو ایک طرف، ان جیسا درویشانہ مزاج بھی انھیں نصیب نہ ہوا۔ وہ لوگ تھے کہ اپنے عہد کا شاہکار صفحۂ ہستی کی زینت بنا کر خود ایک سچے درویش کی مانند سماج کی آخری صف میںدبکے رہے اور اِدھر یہ ہیں کہ ایک کچا سا ناول دے کر کڑک مرغی کی طرح کڑکڑاتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ ناول لکھ گئے اور کسی نقاد کی تعریف کے محتاج نہ ہوئے ، آج بھی ’’گئو دان‘‘ اور ’’اداس نسلیں‘‘ پر گنتی کے چند مضامین ملتے ہیں۔ لیکن یہ دو ناول ہیں کہ ادھر چھپے ہیں، ادھر دھڑا دھڑ تبصرے، جائزے اور نعرے لگ رہے ہیں۔اتنے ناقدین کو اس قدر بولتے دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا نقاد نہیں ہے جو سچی بات بھی کر ڈالے۔ کیا سب نے مکھن لگانے اور مصنف کی بھٹئی کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔
ناول کے اچھے قاری کا اصول ہوتا ہے کہ جو ناول آغاز میں ہی بور کرنا شروع کر دے، اسے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیتا ہے جہاں سے خود اسے بھی اپنی خبر نہ ملے۔ ’’نولکھی کوٹھی‘‘ پڑھتے ہوئے مجھ پر بھی یہی واجب تھا لیکن ایک تو میں خود کو ناول کا اچھا قاری نہیں سمجھتا اور دوسرے طبیعت میں شوقِ فضول کا عنصر بھی حد درجہ پایا ہے، سو اس بوریت کا بھی مزا لیتا رہا اور پڑھتا گیا۔ہر ہر صفحے اور جملے پر یہی خیال آتا تھا کہ جن ناقدین نے اس کی تعریف کی ہے، ضرور ان کا مطالعہ اسی ایک ناول پر محدود رہا ہو گا ورنہ غلطیوں اور کوتاہیوں کے پھٹتے جوبن سے صرف نظر کرنے والا نقاد ان کی تعریف کر کے محض اپنی رائے کا اعتبار گنوانے کے سوا کچھ نہیںپاتا۔معلوم نہیں ہمارے فنکار اور ناقدین کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہ ناول جس پر فن کار نے خونِ جگر صرف نہیں کیا، اس کے رخسار پر نقاد کے مصنوعی غازے سے سرخی نہیں آ سکتی۔ جس ناول کی ماں کے پیٹ میں ہی موت واقع ہو جائے ، اس کے بدن میں نقاد اپنی مسیحائی نہیں پھونک سکتا۔
کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاںادب کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ غلط ہے، بہت پڑھا جاتا ہے لیکن سب باذوق لوگ غیر ملکی ادب پڑھتے ہیں۔ اپنا ادب کم پڑھتے ہیں ۔ اس میں قصور قاری کا نہیں، ادیبوں اور چورن فروش قسم کے نقادوں کا ہے۔ قاری دنیا بھر کے ناول کسی ثقہ بند نقاد کی رائے کے استناد کے بغیر ہی پڑھ ڈالتا ہے کیوں کہ وہ خوداپنے اندر دلچسپی کے تمام عنصر رکھتے ہیں جو پڑھتے چلے جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اردو کے افسانوی ادب کو فنکاروں کی سہل پسندی اور نقادوں کی چرب زبانی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔لکھنے والوں نے جو الم بلم لکھ دیا، نقاد نے اپنی علمیت کا اظہار فرمانے کے لیے اس کی تعریفوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔اگر ناول کے اندر کوئی معنی خیز بات نہیں تو بھی ہمارے نقاداس قدر درباری ذہنیت رکھتے ہیں کہ ناول کے باہر سے تاریخ، سماجیات، فلسفہ، مابعد جدیدیت وغیرہ کے لیکچر جھاڑ کر ناول کو ایک شاہکار ثابت کر دیتے ہیں۔ جو معنی لکھنے والے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے، وہ بھی فن پارے میں سے کشید کر کے دفتر کے دفتر بنادیے جاتے ہیں۔اسی بددیانتی کا یہ انجام ہے کہ ناول کا قاری ان ناقدین کے اس قدر شور شرابے کے باوجود اردو کے ناول پر اب کوئی توجہ نہیں کرتا۔
آمدم برسرِ مطلب، علی اکبر ناطق ایک ابھرتے ہوئے فنکار ہیں۔ اردو کے افسانوی ادب میں ان کا نام خاصا معروف ہو چکا ہے۔ افسانوی مجموعے ’’قائم دین ‘‘ کی کامیابی کے بعد وہ خودبھی اپنے آپ کو اردو کا سرِ فہرست افسانہ نگار سمجھتے بھی اور منواتے بھی ہیں ۔ہمیں بھی ان کے اس دعوے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن اس غرورکا نقصان انھیں خود یہ ہوا کہ انھوں نے لکھنے پر محنت کرنا چھوڑ دیا۔ناول لکھنے بیٹھے تویہ سمجھ لیا کہ افسانے لکھنے کی مشق اور افسانے کی تکنیک کی بنیاد پر ہی ناول کے ساتھ نبھ جائے گی۔اس تن آسانی سے ان کا ناول کہانی کے حساب سے سپاٹ اور پلاٹ کے حوالے سے یک رُخا بن گیا۔نتیجتاً ’’ نولکھی کوٹھی‘‘ کسی بھی باذوق قاری کو بیزار کرنے کی بے انتہا صلاحیت رکھتا ہے۔اگر وہ یہ ناول لکھتے وقت تھوڑا سا بھی سوچ لیتے تو شاید ناول موجودہ حالت سے بہتر ہوتا اور اگر تھوڑا زیادہ سوچ لیتے تو شاید یہ ناول لکھنے سے باز ہی رہتے۔ ناول نگار کو ناول کے متعلق بعض ایسی بنیادی باتوں کا بھی شعور نہیں ہے جن کے بغیر ناول کی تعمیر میں ہی خرابی مضمر رہتی ہے۔ سب سے پہلے کہانی کو دیکھ لیں۔ کہانی ہی ناول کا بنیادی عنصر ہے۔ دنیا کے ہر اچھے ناول کی پہلی خوبی اس کی کہانی ہوتی ہے ، اگر اس کے پاس نئی اور متاثر کن کہانی ہے تو ناول نہ صرف قبولیت کی سند پاتا ہے بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں قدردانی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً سبھی ناول ترجمے کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پہنچتے ہیں۔اس سفر میں زبان کا عنصر تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری صورتِ حال، سیاسی مسائل اور سماجی حالات(یہ سبھی عناصر اردو کے نقاد کو ناول کی تعریف کرتے وقت بہت مرغوب ہیں) وغیرہ بھی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔دیارِ غیرمیں اپنی حیثیت اور فنکاری منوانے کے لیے غریب الوطن ناول کے پاس صرف کہانی کا سہارا ہی بچتا ہے۔ یہ کہانی اگر مضبوط ہو تو ناول کا حلقۂ قرأت سرحدیں پھلانگتا چلا جاتا ہے اور اگر کہانی مضبوط نہ ہو تو پھر اسے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ۔’’فردوسِ بریں‘‘، ’’فسانۂ آزاد‘‘، ’’امرائو جان ادا‘‘،’’گئو دان‘‘، ’’ٹیڑھی لکیر‘‘‘، ’’اک چادر میلی سی‘‘، ’’بستی‘‘، ’’بہائو‘‘اور’’غلام باغ‘‘سبھی اپنی کہانی کی وجہ سے اردو میں زندہ و جاوید ہیں۔ سبھی کہانی کی وجہ سے ہمیں پسند ہیں نہ کہ دوسرے کسی ثانوی عنصر کی بنیاد پر۔ کہانی کا یہی بنیادی عنصر علی اکبر ناطق کے ہاں انتہائی بچگانہ اور لا پروا انداز میں سامنے آتا ہے۔ بنیادی کہانی ولیم کی ہے۔تمام واقعات کو بظاہر اسی کے گرد بُننے کی کوشش کی گئی ہے اور اختتام تک یہی کردار ناول پر حاوی ہے۔ اس کردار کی مرکزی حیثیت کے باوجود سب سے زیادہ اسی کردار کو نظر انداز کیا گیا۔ ولیم کا کردار ہمیں ناول میں جہاں نظر آیا، وہ اول تو اس کی جلال آباد میں انتظامی مصروفیات ہیںجن کا دائرۂ کار 1935ء تک ہی محدود ہے ۔ اس پہلے سال کی روداد ناول کے تین چوتھائی تک حاوی رہتی ہے اور اس کے بعد 1935ء سے لے کر 1981ء تک کا دور وصل کے مہینوں کی طرح اڑتا چلا جاتا ہے۔ تین سال، چار سال، پندرہ سال وغیرہ گزرنے کا ذکر جس طرح آتا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ناول نگار کے پاس کہانی کے واقعات گھڑنے کے لیے نادرہ کار تخیل موجود نہیں ہے اوروہ کسی خاص انجام تک پہنچنے کے لیے بے چینی سے بیانیے میں جست بھرتے جا رہے ہیں۔ ولیم کے علاوہ دو اور ٹریک ہیں ، جن میں غلام حیدر اور مولوی کرامت کے کردار ہیں۔ غلام حیدر کی کہانی تو کسی بھی گھٹیا پنجابی فلم کی کہانی سے اوپر کی چیز نہیں ہے۔ ولن ہیرو سے پنگا لیتا ہے۔ ہیرو برداشت کرنے کی آخری حد تک پہنچ کر ایک دن پھٹ جاتا ہے اور ولن سے انتقا م لے لیتا ہے ۔ اس حصے کے اکثر مکالمے بھی گجر ٹائپ فلموں کا انداز لیے ہوئے ہیں۔ غلام حیدر کی کہانی اس ناول میں اضافی نظر آتی ہے اور محض ولیم کی کہانی کو سنسنی دینے کے لیے شامل کی گئی ہے۔ تعلق صرف اس طرح جوڑا گیا کہ ولیم جہاں پہلی دفعہ پوسٹ ہوا، وہاں غلام حیدر رہتا تھا۔ اس بنیاد پر اس کہانی کو اتنی اہمیت دی گئی کہ بظاہر یہی حصہ حاوی نظر آتا ہے اور ولیم اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ پھریہ سنسنی بھی اتنی سطحی ہے کہ لطف کی بجائے ناول نگار کی کہانی کہنے کی صلاحیت پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا کردار مولوی کرامت ہے۔ یہ بھی ناول میںاضافی ہے۔ پورے ناول میں اس کا مرکزی کردار کے ساتھ تعلق کا جواز نہیں بن پایا ۔ محض کھینچ کھینچ کر مولوی کرامت اور فضل دین کو ایک ایک بار ولیم کے سامنے لایا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں باپ بیٹا ناول میں ایک آزاد حیثیت سے موجود ہیں۔اس قدر غیر ضروری کہ کرامت جب مرتا ہے تو بیانیے کو خبر ہوئے بغیر آرام سے مر جاتا ہے ۔ فضل دین کی موت بھی ایسے ہی دو جملوں میں بھگتا دی جاتی ہے۔ آخرپر جا کر مولوی کرامت کا پوتا جب ولیم کو نو لکھی کوٹھی سے بے دخل کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تین نسلوں سے جاری مولوی کرامت کی کہانی کا مقصد صرف یہ سنسنی خیزڈرامائی انجام تھا۔ ناطق صاحب نے پہلے یہ انجام سوچا، کہ ولیم جسے اختیار دے گا، وہی ولیم کے ساتھ احسان فراموشی کرے گا اور پھر اس انجام تک پہنچنے کے لیے مولوی کرامت کی کہانی شامل کرتے گئے اور یہ بھی نہ دھیان کیا کہ کہانی کے اندر اتنا بڑا حصہ یوں بلاجواز کیسے ٹھہر سکتا ہے۔
ناول سب اصناف سے زیادہ متوازن صنف ہے۔کسی ایک پیچیدہ خیال کو ابھارنے کے لیے کہانی کا تانا بانا بنا جاتا ہے جس کے تمام حصے، اجزا اور عناصر متوازن ہوتے ہیں۔ متوازن سے مراد یہ نہیں کہ سب چیزیں برابر ہوتی ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہر حصے کو اس کی اہمیت کے حساب سے جگہ دی جائے۔ یہ نہیں کہ جو بھی چیز سامنے آئی، اس کی تفصیل بتانی شروع کرد ی۔ کھیت میں گئے تو ایک ایک ڈھیم کی تفصیل دینے لگے۔ باغ میں گئے تو سبھی درختوں کا تعارف شروع کر دیا گیا۔ ناول میں کوئی بھی چیز غیر ضروری نہیں ہوتی اور جو بھی جزئیات بتائی جاتی ہیں ان کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے۔ ناطق صاحب کے ناول میں اصل کہانی ولیم کی ہے اور ولیم ان کے سایۂ عاطفت سے بہت حد تک محروم رہا۔غلام حیدر ، سودھا اور کرامت ذیلی کردار ہیں، انھیں نسبتاً بہت زیادہ وقت دیا گیا لیکن انھوں نے مرکزی کردار کے خدو خال ابھارنے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا اور نہ ہی یہ مرکزی کہانی کے لیے ناگزیر کردار ہیں۔ ان کو دیا گیا وقت ضائع ہوا اور ناول کے توازن کو پوری طرح توڑ گیا۔
ناول بیانیے کا دوسرا نام ہے اور بیانیہ ترتیب پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ور ہر نیا واقعہ پچھلے واقعات کے ساتھ منطقی طور پر مربوط ہو کر آتا ہے۔ایک چیز کے متعلق جو تفصیل بتا دی گئی ہو، اس سے رو گردانی نہیں کی جا سکتی۔ اچھے ناول نگار کبھی بھی اس ترتیب/اس منطق کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ علی اکبر ناطق صاحب ناول لکھنے تو بیٹھ گئے لیکن ناول کے اس اہم ترین عنصر کا انھیں شعور ہی نہیں ہے۔انھیں یہ یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا بتا کے آئے ہیں اور آگے چل کر اسی سے مختلف اور بعض اوقات متضاد بیان دے جاتے ہیں۔ ناول میں بہت سی جگہوں پر ترتیب کی یہ خرابی تعمیر میں خرابی کی صورت ظاہر ہوتی ہے:
۱۔ص:18۔ پیراگراف کے شروع میں بتایا گیا کہ غلام حیدر کو لینے کے لیے رفیق پاولی موجود تھا اور چراغ تیلی اور جانی چھینبا بھی پاس کھڑے تھے۔یعنی کُل تین لوگ۔ سات سطر کے بعد غلام حیدر کے ارد گرد بیس لوگ گھیرا ڈال لیتے ہیں۔بگھی بھی پہلے ایک تھی، اب تین ہو گئیں۔ ان بیس لوگوں اور تین بگھیوں کا پہلے کوئی ذکر نہیں آیا۔
۲۔ ص:52۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چراغ دین کے قتل کے بعد غلام حیدر چوتھے دن چراغ دین کے گھر پہنچا۔ اور آگے ص:56پر تھانے میں جا کر کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، وقت بالکل نہیں ہے۔ چار دن کی تاخیر سے تھانے پہنچنے والا آدمی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔اتنا ہی وقت کی کمی کا احساس تھا تو اسی دن ہی کیوں نہ پہنچا۔ اور پھر ہمیں ناول نگار نے یہ بھی اطلاع نہیں دی کہ دوسرے اور تیسرے دن غلام حیدر کیا کرتا رہا جو نہ موقع پر پہنچ سکا اور نہ ہی تھانے پہنچا۔
۳۔ چراغ دین کے قتل کا سن کر راج محمد جلال آباد سے سیدھا قصور کے لیے نکل گیا تا کہ شریفاں کو چراغ دین کے قتل کا بتا سکے۔ وہ پہلے دن نکلا اور چوتھے دن قصور پہنچا۔ ادھرغلام حیدر نے چراغ دین کی بیوہ کے لیے پہلے دن پانچ سو بھجوایا(ص: 40، سطر14)، پھر جب چوتھے دن وہاں پہنچا تو مزید پانچ سو اسے دیا(ص: 53، سطر 6)، یہ دونوں رقوم ملا کر ایک ہزار بنتی ہیں۔ وقت کے حساب سے جب غلام حیدر چراغ دین کی بیوہ کو دوسرے پانچ سو روپے دے رہا تھا، اس وقت راج محمد قصور میں شریفاں کو بتا رہا تھا کہ ’’غلام حیدر نے چراغ دین کے قتل کا سنتے ہی دس ایکڑ زمین دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ پورے ایک ہزار روپے تو پہلے ہی دے دیے ہیں۔ ‘‘
ص:61۔سوال یہ بنتا ہے کہ اسے یہ دوسری رقم کا علم کیسے ہوا۔
۴۔ ص:88، سطر:13پر ولیم موڑھے سے اٹھتا ہے اور سودھا سنگھ کی چارپائی پر پائنتی کی طرف بیٹھ جاتا ہے۔ آگے ص:90، سطر 16 پر لکھا ہے:’’اس کے بعد ولیم موڑھے سے اٹھ کھڑا ہو گیا ۔‘‘ پچھلی دفعہ موڑھے سے اٹھنے کے بعد وہ دوبارہ بیٹھا ہی نہیں، تو ایک بار پھر اس کے اٹھنے کا سوال کیسے پیدا ہوا؟
۵۔ص:103، سطر:12پر مولوی کرامت کے متعلق لکھا ہے کہ ’’اول تو اسے کل ہر حالت تحصیل جانا تھا۔ ‘‘ اس جملے کے بعد مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ اگلے صفحے تک مکالمہ جاری رہتا ہے اور مکالمہ ختم ہوتے ہی اسی دِن بلکہ اُسی وقت مولوی کرامت خیر دین تانگے والے کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ص:105،سطر:1۔
۶۔ص:130،سطر:1پر بتایا جا چکا ہے کہ چراغ دین کے ساتے کو دو دن گزر چکے ہیں۔ چراغ دین مرا تھا شیر حیدر کے مرنے کے تین دن بعد۔ یعنی کُل ملا کر12دن گزر چکے ہیں۔ آگے چل کر غلام حیدر شہر جاتا ہے ۔ اس کے اِس جانے کا تذکرہ ص:103پر مولوی کرامت کر بھی چکا ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ وہی بارہواں دن ہے۔ لیکن غلام حیدر اپنے دوست شیخ نجم کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ شیر حیدر کو مرے آج چھٹا دن ہے ۔ ص:120، سطر:3۔ یہ کیسا بیٹا ہے جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے باپ کو مرے ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں۔
۷۔ غلام حیدر کے گائوں شاہ پور پر حملے کے دوران سودھا سنگھ کا ایک خاص آدمی مارا گیا تھا۔ پہلی دفعہ ص:168، سطر :10پر بتایا گیا ہے کہ یہ آدمی دَما سنگھ تھا ۔ آگے ص: 184، سطر:11پر اِس آدمی کا نام بدل کر متھا سنگھ بن جاتا ہے۔ تیسری دفعہ ص:261، سطر:15پر اس آدمی کا نام رنگا بن جاتاہے۔ شاید کردار کے مرنے کے بعد ناطق صاحب اخبار میں اشتہاربرائے تبدیلی نام دے کر اس کا نام تبدیل کرواتے رہے ہیں۔
۸۔ ص: 188پر ملک بہزاد کا پہلی بار ذکر آتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ شیر حیدر کی وفات کے وقت ’’ملک بہزاد نے غلام حیدر کو بار بار یہ بات باور کرائی تھی، پتر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتانا۔‘‘ حالانکہ ناول میں اس سے قبل کہیں بھی ملک بہزاد کا ذکر تک نہیں آیا تھا۔ اگراتنا اہم کردار تھا، اس کا ذکر پہلے ضرور کرنا چاہیے تھا۔
۹۔ص: 203پر ولیم اپنے افسر سے کہتا ہے:’’سر ایک کافی کا کپ مزید مل جائے گا۔‘‘ مزیدسے ظاہر ہے کہ پہلے ایک کپ پیا جا چکا ہے۔لیکن اس پورے منظر میں پہلے کوئی کپ نہ تو پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی ولیم نے نوش فرمایا ہے۔ ناطق صاحب کافی کے ایک کپ کے پیسے بچا لے گئے ہیں۔
۱۰۔ ص:196،سطر:10پر لکھا ہے:’’میرے بھائی کے بیٹے! یہ رشوت کا خون ان کے منہ کو بھی لگ چکا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے ، جہاں دیسی دلا دس لیتا ہے، یہ گورا بیس لیتا ہے۔ ‘‘ اور ص:309سطر:21پر لکھا ہے :’’ان سفارشوں کے عوض مولوی صاحب نے کسی سے پیسے تو نہیں پکڑے تھے، جس کا اُس وقت رواج بھی کم تھا۔‘‘
۱۲۔ ص:221پر ولیم کہتا ہے : ’’مجھے یہاں آئے چھٹا مہینہ ہے ۔‘‘ ولیم دسمبر کی سخت سردی میں آیا تھا، اس حساب سے جون کامہینہ بنتا ہے۔ 2صفحے آگے ص:223پردوسری سطر میں لکھا ہے کہ ہفتہ پہلے سردار سودھا سنگھ اور عبدل گجر کے بندوں کی گرفتاری اور مال کی ضبطی ہوئی۔ یہ واقعات فروری میں ہوئے تھے۔ ص:234پر لکھا ہے کہ ’’مارچ کا آغاز تھا۔‘‘(اس حساب سے ولیم کو جلال آباد تعینات ہوئے تین مہینے ہوئے ہیں۔ جب کہ وہ فروری میں کہہ رہا ہے کہ اسے چھ مہینے ہوئے ہیں۔ اگر فروری سے چھ مہینے پیچھے دیکھا جائے تو اگست بنتا ہے اور اگست میںدھند اور کہر نہیں ہو سکتے۔ یہاں صاف ظاہر ہے کہ ناطق صاحب خود بھی حساب گردشِ لیل و نہار بھول گئے ہیں۔)
۱۳۔ ص: 262پر سب سکھ صلاح کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے کی چار تاریخ کو پیشی ہے اور فیروز پور عدالت میں کیسے جانا ہے۔ اگلے باب کی پہلی سطرمیں بتایا گیا کہ جون کا آغاز ہو گیا ہے۔ ص:265۔ یعنی جون کی چار تاریخ کو پیشی تھی۔ لیکن ص:279پر جولائی کا مہینہ ہے اور ابھی تک پیشی پر نہیں گئے۔
۱۴۔ ولیم کئی دفعہ کہہ چکا کہ جلال آباد میں کوئی کلب نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کیوں کہ وہاں
ولیم اکیلا انگریز ہے۔ لیکن ص:312پر لکھا ہے کہ :’’نہ ہی کیتھی کو یہ بات منظور تھی کہ ولیم ڈیوٹی کے وقت کے علاوہ کسی کلب میں اس کے بغیر جائے ۔‘‘ جب کلب ہی نہیں تو پھر ولیم کا کلب میں جانے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور ’کسی کلب ‘ کے الفاظ تو یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہاں ایک سے زیادہ کلب ہوں۔
۱۵۔نواز الحق کی اسٹنٹ کمشنری کے آرڈر جاری ہوئے :’’انھیں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جھنگ شہر کی افسری کا پروانہ دے دیا گیا جہاں دیگر کاموں کے ساتھ بعض مسالک اور ان کے عقائد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا تھیں۔ ‘‘ ص:401۔ یہاں نواز الحق کا باب ختم ہوتا ہے اور پانچ صفحے بعد دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہلی ہی سطر پر لکھا ہے۔ ’’اوکاڑہ تحصیل میں نئے اسسٹنٹ کمشنر کے آتے ہی کمپلیکس میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ یہ شہر منٹگمری کی سب سے بڑی تحصیل تھی۔ ‘‘ص:406۔ (ناطق صاحب شاید بہتر جانتے ہوں کہ جھنگ جانے والا افسر اوکاڑہ کیسے جا پہنچتا ہے۔ )
ناول نگار کو خاص دھیان دینا پڑتا ہے کہ ناول کے بیانیے کا زمانہ کون سا ہے اور پھر اس زمانے اور ماحول کے سماجی ، معاشی، تاریخی حالات کو اپنے شعور کا حصہ بنانا پڑتا ہے تب جا کر ناول کے صفحات پر وہ زمانہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ نما ہوتا ہے۔جیسا کہ ’’بہائو‘‘میںقبل از تاریخ کا زمانہ اور ’’کئی چاند تھے سرِ آسماں‘‘ میں انیسویں صدی کا دلی اپنی تمام تہذیبی جزئیات کے ساتھ متحرک نظر آتے ہیں اور کوئی پہلو تشنہ، کوئی گوشہ خفیہ نہیں رہتا۔ اُس زمانے کے حالات پر عبور حاصل کیے بغیر لکھا گیا ناول پھسپھسا ہوتا ہے اور کسی بھی زمانے کے تعین کے بغیر زمانی خلا میں معلق رہ جاتا ہے۔ ایسے ناول کی فضا اور ماحول دھندلے ہوتے ہیں اور ناول کے بیانیے کو زندگی کی حرارت نہیں بخش پاتے۔ ناطق صاحب نے زمانہ1935ء کا منتخب کیا ہے اور ماحول فیروز پور کی تحصیل جلال آباد کا۔ لیکن ان سے ناول کے اندر یہ زمانہ اور ماحول پوری طرح زندہ نہیں ہو سکے۔ بظاہر تو انھوںنے جزئیات نگاری کا خاصا خیال رکھا ہے لیکن وہ جو1935ء کی فضا ہے وہ کہیں بھی ناول کے صفحات پر جلوہ نما نظر نہیں آتی۔ کاغذی بیان ، کاغذی ہی رہتا ہے۔ ان جزئیات کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ناطق صاحب نے بغیر کسی گہرے مطالعے کے (جو ایسے ہی موضوعات پر لکھنے والی قرۃ العین حیدر کا خاصہ ہے)محض ذاتی علم پر بھروسہ کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پر بری طرح ٹھوکر کھائی۔ مثال کے طور پر انھوںنے ایک جگہ کیتھی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیتھی نے ولیم کو اس لیے پسند کیا :’’ولیم سے شادی کرنا کیتھی کے لیے کسی پرنس کا ہاتھ آ جانے سے کم نہ تھا…انگلستان میں رہنے والی نو عمر لڑکیاں اس تاک میں رہتیں کہ کسی طرح سی ایس ایس کرنے والے لڑکے کو پھانس لیا جائے۔ ‘‘ ناطق صاحب کو یہ کون بتائے کہ CSSکا امتحان پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا۔ برٹش دور میں اس امتحان کو آئی سی ایس کہا جاتا تھا۔ ایک سیدھی اور سامنے کی فاش غلطی یہ کی کہ دوسری جنگِ عظیم میں جرمنی اور روس کو اتحادی دکھا دیا۔ روس خود مشرقی یورپ کا حصہ ہے لیکن مصنف نے انھیں دو الگ خطے دکھا دیا۔ ’’ہٹلر کی حکومت نے مشرقی یورپ میں ایک وسیع اور جدید سلطنت ’’لونگ اسپیس ‘‘ (لیبن سروم) کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے یہ خیال اپنے لوگوں پر واضح کیا تو جرمن لیڈروں نے یورپ پر جرمنی کے تسلط کے لیے جنگ کو ضروری قرار دے دیا۔ سویت یونین کی غیر جانبداری حاصل کرنے کے بعد جرمنی نے یکم ستمبر انیس سو انتالیس میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگِ عظیم کا آغاز کر دیا…ادھر ایک ماہ کے اندر جرمن نے سویت فوجوں کے اتحاد سے پولینڈ کو شکست دے دی۔پولینڈ جرمنی اور سویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔‘‘جیپ 1941میں ایجاد ہوئی تھی،سول مقاصد کے لیے 1945ء میں متعارف کروائی گئی لیکن ناول کے صفحات میں اپنی ایجاد سے قبل 1935ء میں ہی فراٹے بھرتی نظر آتی ہے۔(ص:33)
The original Jeep was the prototype Bantam BRC. Willys MB Jeeps went into production in 1941[1] specifically for the military. The first civilian models were produced in 1945.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep(
کِنو 1935ء میں کیلیفورنیا میں ایجاد ہوا تھا، اور ہندوستان میں پہلی بار 1940میں کاشت کیا گیا۔
After evaluation, the kinno was released as a new variety for commercial cultivation in 1935. In 1940, Punjab Agriculture College and Research Institute, Lyallpur (Pakistan) introduced the kinno. In India this variety was introduced by J. C. Bakhshi in 1954 at the Punjab Agricultural University, Regional Fruit Research Station, Abohar. It has become an important variety in the Punjab provinces of both India
andPakistan.
)http://www.pakistaneconomist.com/pagesearch/Search-Engine2011/S.E483.php(
ناول میں یہ کِنو 1935ء میں کھایا جا رہا ہے(ص:108) اور کھانے والوں کے انداز سے پتا چلتا ہے جیسے بہت مدت سے کِنو متعارف ہو چکا ہے۔مسجد کے ریڈی میڈ مینار (ص:58)دیکھ کر بھی یوں لگا جیسے آج کے زمانے کی مسجد دیکھ رہے ہوں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:’’احاطے کی دیواریں پکی اینٹ سے چن کر بیس فٹ تک اونچی کی گئیں تھیں لیکن ان پر کسی وجہ سے پلستر نہیں کیا گیا تھا۔‘‘ص:20۔ 1935ء کے زمانے کی جو تعمیرات دیکھی گئی ہیں ان کی دیواروں پر پلستر کا رواج نہیں تھا اور خاص طور پر گائوں دیہات میں تو پلستر کانام ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ بھی احاطے کی اتنی بڑی دیوار کو کس نے پلسترکرنا تھا۔ یہ بھی مان لیا کیا کہ پلستر نہ ہونا ایک عیب تھا لیکن خود ناطق صاحب کا قلم دو سطروں کے بعد ان کے خلاف گواہی دینے آ پہنچتا ہے ۔لکھتے ہیں:’’ویسے بھی دیواروں کو آرائش یا پلستر کرنا عموماً دیہاتوں میں ضروری نہیں سمجھا جاتا۔‘‘ اس جملے کا صیغہ بتاتا ہے کہ ناطق صاحب نے آج کے زمانے کی بات لکھی ہے۔ اور اگر آج پلستر کا رواج نہیں ہے تو پھر 80سال پہلے اس کے نہ ہونے کا کیا سوال ہے۔اسی طرح انھیں خط اور تار کے فرق کا احساس بھی نہیں۔ ولیم کیتھی کو ایک لمبا چوڑا خط لکھتا ہے اور نجیب شاہ کے حوالے کر کے بذریعہ تار کیتھی کو روانہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تار کے ذریعے اتنا طویل خط اور وہ بھی محبت نامہ! تصور کرتے ہوئے الجھن ہوتی ہے۔
تاریخی لحاظ سے ان مسائل کے ساتھ ماحول کے متعلق بھی کئی جگہ پر ناطق صاحب ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اردو افسانے میں پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، بلونت سنگھ، سید رفیق حسین، ابو الفضل صدیقی،احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد جیسے افسانہ نگاروں کی ، دیہی معاشرت پر بے مثال تخلیقات کی وجہ سے ہر نئے افسانہ نگار کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ وہ دیہی ماحول کے متعلق افسانے لکھ کر اپنا نام اردو افسانے کی تاریخ میں اُن افسانہ نگاروں کے ساتھ سنہری حروف میں رقم کروا لے۔ اس ضمن میںپہلا قصور اردو کے ان شہری قارئین کا ہے جن کا دیہی معاشر ت سے کوئی تعلق تو ہوتا نہیں لیکن جب کوئی افسانہ دیہی معاشرت پر لکھا جائے، یہ قارئین اس کی بے تحاشا تعریف کرتے چلے جاتے ہیں۔ خواہ وہ افسانہ دیہی ماحول کو پوری خوبصورتی سے پیش کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔غلام الثقلین نقوی اور محمد منشاء یادکے اکثر افسانوں کی بے جا توصیف اس بات کی مظہر ہے کہ دیہاتی زندگی کا محض ذکر ہی اردو کے ناقدین کو کشش کرتا ہے۔ دوسری غلطی ان افسانہ نگاروں کی ہے جن کا اپنا سماجی پس منظر دیہاتی ہے۔ ایسے افسانہ نگار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر افسانہ نگار کا اپنا اور افسانے کا پس منظر دیہی ہو تو افسانے کو فن پارہ بنانے کے لیے یہی بہت ہے ۔ کہانی کی ندرت ضروری نہیں اورنہ ہی اس کی فنی باریکیوں پر توجہ کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ افسانہ نگار اپنے ارد گرد کے معاشرے کا بھی صحیح طرح سے مشاہدہ نہیں کرتے ۔ بس لکھ دیا کہ گائوں ہے اور فصلوں ، جانوروں کا ذکر کر دیا، کرداروں کے نام ماجھا گاما رکھ دیے اور سمجھ لیا کہ دیہی معاشرت کی عکاسی ہوگئی ۔ کہانی، پلاٹ،زبان، مکالمے، کردار اور جزئیات نگاری وغیرہ کا شعور تک نہ ہوتو بھی اپنی اسی خوبی پر پھولے نہیں سماتے۔ ناطق صاحب کا شمار بھی ایسے ہی فنکاروں میں ہوتا ہے جو دیہی معاشرت کے متعلق لکھنے بیٹھے ہیں لیکن خود انھوں نے اپنے دیہات کا گہرامشاہدہ نہیں کیا ہوا۔ انھیں یہ تک نہیں معلوم کہ ماحول کی پیش کش میں ایسا کوئی عمل یا منظر نہیں پیش کرنا چاہیے جو اس ماحول کے جغرافیے ، موسم یا عام عادات کے مطابق نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی چیز بیانیے کا حصہ بنے گی تو یہ ایک فاش غلطی تصور کی جاتی ہے۔ ان کے افسانوی پس منظر کی دنیا عام طور پر دیہاتی ہوتی ہے اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ ان کا دیہاتی ماحول کا علم بہت وسیع ہو گا لیکن انھوں نے دو جگہ ایسی فاش غلطیاں کی ہیں جو زمیندار گھرانے کا بچہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ ناول کے آغاز پر سخت سردی اور دھند کا موسم دکھایا گیا ہے۔ جس رات کو سودھا سنگھ کے آدمیوں نے غلام حیدر کے کھیت پر حملہ کیا، اس رات نیاز حسین کے بیان کے مطابق سخت دھند اور کہر تھی۔(ص:39)اس رات کو غلام حیدر کی مونگی کی20ایکڑ فصل ویران کر دی گئی۔ یہ سب بیان درست ہے۔ بس اگر یہ معلوم نہ ہو کہ مونگی کی فصل ساونی ہے جو جولائی میں کاشت ہوتی ہے اور ستمبر میں کاٹی جاتی ہے۔ اس دوران سخت کہر اور دھند ناول کے پروڈیوسر صاحب کہاں سے لے آئے، یہ ہمیں خبر نہیںیا پھرانھوں نے سخت سردی میں مونگی کیسے اگا لی، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ دوسری جگہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے یہ طے ہے کہ فروری کا مہینہ ہے ،وہاںلکھتے ہیں:’’اکا دکا لوگ جاگ اٹھے تھے، جوادھرادھر کام میں اور اپنی فصلوں میں ہل وغیرہ جوتنے کے لیے نکل رہے تھے۔‘‘ص:205۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ناطق صاحب نے اتنا تو سن رکھا ہے کہ ہل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے ، جسے جوتا جاتا ہے،لیکن انھیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کب اور کہاں جوتا جاتا ہے ۔زمین اور گائوں سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ فروری شریف میں حضرت ہل صاحب کو جوتنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسرے کھیتوں میں ہل جوتنے کا تو سنا ہوا ہے، یہ فصلوں میں ہل جوتنے کا کام تو شاید کسی مخبوط الحواس کو بھی نہ سوجھے۔صاف معلوم ہوتا ہے کہ دیہی زندگی کے متعلق ناطق کا مشاہدہ ذرا بھی نہیں ہے، بس فیشن کے طور پر گائوں کی زندگی پیش کرناپوز کرتے ہیں ۔
انھیں آئی سی ایس کا مزاج بھی بالکل نہیں معلوم۔ بہت طویل مثالیں دینے سے مضمون کی کوفت ہی بڑھے گی۔ بہت سی جگہوں پر یہ ناگوار احساس ہوتا ہے کہ ناطق صاحب کو ایک آئی سی ایس کے مزاج کے متعلق ذرا سا بھی شعور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل بیان دیکھیے:’’کچھ ہی دیر بعد ولیم نے محسوس کیا کہ کام کرنے والے کچھ لوگوں کی نظر ان پر پڑ چکی ہے اور وہ اسے اپنا کام چھوڑ کر بغور دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ولیم کو ان کی یہ عادت بری لگی۔ خاص کر ہندوستانیوں کی ،چاہے وہ مسلمان ہوں یا سکھ، ان کی اس مشترکہ عادت سے اسے سخت نفرت تھی۔ (اس جملے کے حسن پر بھی غور
کیا جائے۔)وہ کسی بھی چیز کو عجوبے کی طرح دیکھنے کے عادی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں انتہائی بے ہودہ اور غلط مگر حتمی تاویلیں کرنے کے ماہر بھی ۔‘‘ص:83۔قاری دیکھ سکتا ہے کہ یہ سوچ آئی سی ایس افسر کی نہیں ہوسکتی جو مقامی لوگوں کی نظروں کی چبھن محسوس کر رہی ہے ۔ یہ کمال خیال مقامی مصنف کا ہے۔اسی طرح ص:88پر ولیم جب سودھا سنگھ کی چارپائی کے پائینتی بیٹھتا ہے تو سودھا سنگھ کو غصہ آتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اتنی جرأت جھنڈو والا میں خدا ہی کرسکتا تھا۔ حالانکہ پنجابی کلچر میں کم مرتبہ آدمی پائینتی کی طرف بیٹھتا ہے۔ اگر و لیم خود کو کم مرتبہ ثابت کر رہا ہے تو سودھا سنگھ کیوں چراغ پا ہورہا ہے۔ جب کہ آئی سی ایس پائنتی بیٹھے گاہی کیوں۔ اس کے بیٹھنے پر تو سودھا سنگھ کو اُٹھ جانا چاہیے تھا۔ سودھا سنگھ اور اس کے سب ساتھی حقیر سے تھانے دار سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اتنا چھوٹا طبقہ ہے اور ان کے درمیان انگریز اسسٹنٹ کمشنر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور ناطق صاحب جانتے ہی نہیں کہ اس طبقے پر انگریز اور وہ بھی انگریز افسر کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔
ماحول کے متعلق ایک غلطی ایسی ہے کہ تصور کر کے عجیب قسم کی ابکائی آ جاتی ہے۔گڑ بنانے والے لوگوں کے پاس ولیم اور اس کے سپاہی پہنچے ہیں۔ آگے یوں لکھا ہے:’’ایک آدمی چونبے کے کنارے بیٹھا کُڈھن سے اُ س میں پیڑھ پھینک رہا تھا جس کی تیز آگ کڑاہے میں پڑی ہوئی پت کو پکا رہی تھی۔ چھاننی اور کڑچھے سے اسے بار بار ہلایا بھی جا رہا تھا۔ گنڈ میں پکی ہوئی راب سے ایک سِکھڑا رنبی کی مدد سے گُڑ کی ڈلیاں کاٹ کاٹ کر بنانے لگا۔ یہ پورا منظر ولیم کے لیے انتہائی پُر کشش تھا۔ دونوں سنتری بیٹھے لسی پینے کے ساتھ گُڑ بھی کھانے لگے۔‘‘ ص:180۔(گرم گرم گُڑ کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پینے کا تصور ایسا ہے کہ کسی بھی معقول آدمی کو ابکائی آ سکتی ہے۔ ناطق صاحب دیہاتی کلچر پر کہانی لکھنے کے ماہر کہلوانا پسند کرتے ہیں لیکن ہزاروں دیگر باریک باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں جانتے کہ لسی میٹھی چیزوں کے ساتھ نہیں پی جاتی۔ کڑوی یا کھٹی چیز کے ساتھ پی جاتی ہے۔ گڑ کے ساتھ لسی نہ کہیںرائج ہے نہ ہی پی جاسکتی ہے۔معاشرتی رواج کے ساتھ ساتھ دیسی حکمت بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔)
ماحول کے متعلق ایک اور بہت ہی فاش غلطی ہے بلکہ میں تو اسے فحش غلطی کہوں گا۔ اس غلطی سے واضح معلوم ہو تا ہے کہ ناطق صاحب کا گائوں کے ماحول سے دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ بس فیشن کے طور پر گائوں کی زندگی کو اپنی کہانی میں پیش کرتے ہیں۔ گائوں میں زمیندارہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔اس زمیندارے کے لیے مقامی کلچر میں کچھ خاص قومیتیں اور ذاتیں پیدائشی طور پر ماہر گِنی جاتی ہیں اور کچھ خاص طور پر زمیندارے کے لیے نامناسب شمار کی جاتی ہیں۔ ان ذاتوں میں بھی سب سے نامناسب ذات پاولی سمجھی جاتی ہے۔ عام طور پر اگر زمیندار گھرانے کا کوئی لڑکا حد درجہ پھوہڑ نکلے تو اسے پاولی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یعنی زمیندارہ سنبھالنے کے لیے نامناسبت کے لحاظ سے پاولی مثالی حیثیت رکھتا ہے۔اور ادھر اس بات سے بے خبر ناطق صاحب اپنے لاعلمی کے شاہکار بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔’’غلام حیدر کو ان معاملات میں کچھ تجربہ نہیں تھا۔اس کی زندگی کسی اور ہی تربیت کا نتیجہ تھی ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کاروبار رفیق پاولی کو سونپ کر چند دنوں بعد لاہور چلا جائے گا۔ رفیق خود ہی مزارعوں کے ساتھ حساب کتاب کر تا رہے گا۔ ویسے بھی شیر حیدر کی زندگی میں نوے فیصد کام رفیق پاولی نے اپنے ہی ذمے لے رکھے تھے۔‘‘ص:35۔ جس زمیندار کو ایک پاولی زمیندارہ سنبھالنے کے لیے سب سے مناسب آدمی لگتا ہو، وہ اس کلچر سے نہیں ہو سکتا۔ غلام حیدر تو پڑھا لکھا ہے، زمیندارہ سے عدم واقفیت اس کا عذر بن سکتی ہے لیکن خود شیر حیدر تو خالص زمیندار تھا۔ اسے کوئی اور کاشت کار طبقے کا آدمی چھوڑ، باقی گیارہ ذاتوںمیں سے بھی کوئی ایسا نہیں ملا تھا جو یہ کام سنبھال لے۔ پھر یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن غلام حیدر کے ارد گرد اس کے اپنے آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو کاشت کار گھرانے کا ہو۔ سب ماچھی، پاولی وغیرہ ہی ملتے ہیں۔تو کیااس کی زمینوں پر ہل بھی ایسے ہی لوگ چلاتے تھے۔اور اگر کاشت کار ذاتیں ہل چلاتی تھیں تو سماجی مقام و مرتبے میں وہ غلام حیدر کے زیادہ قریب کیوں نہیں، غیر کاشت کار ہی کیوں قریب ہیں۔
بیانیے میں کسی بھی ناول نگار کے لیے غیر جانبدار رہنا امتحان ہوتا ہے۔ ناول میں اچھے برے سبھی کردار پیش ہوتے ہیں، سبھی ناول نگار کی اپنی تخلیق ہوتے ہیں، اور کسی خاص کردار کی طرف جھکائو یا طرف داری ناول کو تخلیق کے درجے سے گرا کر پروپیگنڈا کی سطح پر لے آتی ہے۔ کوئی بھی مصنف جب اپنے کچھ کرداروں کی حمایت کرتا ہے اور دوسروں کی مخالفت تو وہ بیانیہ ایک ایسا یک طرفہ بیان بن جاتا ہے جو کسی خاص گروہ کے نمائندے نے اپنے مفادات یا تاریخ کے تحفظ کے لیے تعمیرکیا ہوتا ہے۔نسیم حجازی قسم کے تاریخی ناول اسی کی مثال ہیں۔ ناطق صاحب کو اس بات کا ذرا بھی شعور نہیں کہ انھیں کرداروں کے مذہبی پس منظر سے الگ رہنا چاہیے۔ وہ خود مسلمان ہیں ، ٹھیک ہے لیکن ناول کے اندر ان کو مذہب ایک طرف رکھ کر فن کے ساتھ وفاداری نبھانی چاہیے اورفن کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف داری نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر وہ بھیشم سا ہنی کا ’’تَمَس ‘‘ ہی پڑھ لیتے تو انھیں سلیقہ آ جاتا کہ تقسیم کے وقت دونوں قوموں کے جذبات کیسے پیش کرنے ہیں۔فنکار کا کام قوموں، قبیلوں اور مذاہب سے بالاتر ہو کر پوری انسانیت کی نمائندگی کرنا ہے اور انھیں ایک دوسرے کے ساتھ انسانی رشتے کی بنیاد پر جوڑنا ہے۔ اگر فنکار ہی انسانوں کے درمیان تعصب کو ہوا دینے لگے تو پھر انسانوں کے درمیان نفرت، کینہ پروری اور بغض و عناد جیسی صفات فخر کی علامت بن کربرتری کا معیار قرار پائیں گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناطق صاحب نے کس کس جگہ اپنے اس تعصب کو صفحات کی زینت بنایا ہے۔ ان کا یہ ناول اور اقبال کا مصرعہ ’’کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر ہم نے‘‘ دونوں ایک ہی جیسے تعصب انگیز نظر آتے ہیں۔
۱۔ ہیلے اپنے جونئیر ولیم کو مقامی لوگوں کا مزاج سمجھا رہا ہے۔’’ان کے سینے دریائوں کی طرح چوڑے اور مزاج اس کے بہائو کی طرح تیز ہیں…پنجابی مسلمان معقول اور بات کو جلد سمجھ لینے والے ہیں۔ جب کہ سکھ احمق اور ہر وقت اپنے ہی نقصان کے درپے رہتے ہیں۔‘‘ص:32
۲۔ ایک اور جگہ سردار سودھا سنگھ کی بیوی اسے روک رہی ہے اور دیکھ لیجیے کہ ناطق صاحب اپنے مذہب والوں کی حمایت کے لیے کس طرح اس کے منہ میں اپنے الفاظ ٹھونس رہے ہیں:’’یہ مُسلے مرجانے بڑے بُرے اور چیر پھاڑ کر کھاجانے والے کتے ہوتے ہیں۔ سنا ہے دشمنی اور لڑائی بھڑائی میں اِن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ‘‘ص:264
۳۔ سردار سودھا سنگھ اپنے دشمن کے سامنے ہے ۔ غلام حیدر کو بندوق ہاتھ میں لیے دیکھتا ہے تو یوں سوچتا ہے:’’ بنتو سچ کہتی تھی۔ یہ مُسلے بڑے بگھیاڑ ہوتے ہیں۔ ان کے بچے بھی بگھیاڑ ہوتے ہیں۔ آخر یہ غلام حیدر مجھے کھا ہی گیا۔ ‘‘ص:286۔ (مسلمانوں کی بالواسطہ تعریف اپنی جگہ، یہ بات بنتو نے کبھی ناول کے اندر کہی ہی نہیں تھی۔)
۴۔جودھا پور میں کل پچاسی مرد ہیں ، ادھر سردار شمشیر سنگھ دو سو مسلح بندے لے کر جودھا پور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی شمشیر سنگھ کی سوچ دیکھیں:’’شمشیر سنگھ جانتا تھا، حالات جتنے بھی سکھوں کے حق میںہوں، مُسلے بہر حال ایسے بچھو تھے جو کسی نئے طریقے سے بھی ڈنک مار سکتے تھے۔‘‘ص:366۔(صاف نظر آتا ہے کہ یہ جملہ اس مصنف نے لکھا ہے جس کا ایمان ہے کہ ایک سچا مومن، دس کفار پر بھاری ہوتا ہے۔ )
۵۔ ایک جگہ پر بیانیے نے ایسی نہج پکڑی کہ ناول نگار پسِ پردہ پشت پناہی کرنے کی بجائے کھُل کر مسلمانوں کی حمایت پر اُتر آیا۔ لکھتے ہیں:’’اب چھت پر بیٹھے ہوئے بندوق والوں کو کھُل کر فائر کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن کارتوس کم ہو گئے تھے۔ مگر اُس کا اندازہ خدا کا شکر ہے، شمشیر سنگھ کو نہیں تھا۔‘‘ص:369۔(یہاں خدا کا شکر ناطق صاحب نے ادا کیا ہے اور کھُل کر بتا دیا ہے کہ مصنف مسلمانوں کی صف میں ہی کھڑا ہے اور سکھوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح دلوانے کا پوری طرح خواہش مند ہے۔)
۶۔ اگلے ہی صفحے میں اس تعصب نے ایک اور عجوبہ دکھایا ہے:’’کاہنا سئیو نے تاک کر ایک گولی ماری کہ سیدھی آ کر رفیق پاولی کے دل پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اِس گولی کا لگنا تھا ، مسلمانوں نے نعرے بازی بلند کر دی۔ انھوں نے محسوس کیا کہ مر تو جانا ہے، کیوں نہ زیادہ سے زیادہ سکھوں کو لے کر مریں۔ ‘‘چھ سطروں کے بعد لکھتے ہیں:’’اسی وقت چھت پر سے ایک گولی شمشیر سنگھ کے ماتھے پر آ کر لگی اور وہ گھوڑے سے سیدھا زمین پر آ پڑا۔ یہ دیکھ سکھوں کے حوصلے پست ہوگئے۔ انھوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ‘‘ص:370۔(ایک فریق کا سربراہ ملا تو انھیں تقویت ملی، دوسرے کا سربراہ مرا تو وہ بزدل ہو گئے۔ خدا قسم، نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم کی وہ تقریر یاد آ گئی جہاں قاسم کہتا ہے کہ ہم لوگ سالاروں کے لیے نہیں ، خدا کے لیے لڑتے ہیں، اس لیے سالار مر بھی جائے تو ہم لڑتے رہتے ہیں اور کافر اپنے سالار کے لیے لڑتے ہیں، ان کا سالار مر جائے تو وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین)
اس ناول کو A Love Letter to RAJکہا گیا ہے اور مندرجہ بالا قسم کے جملے دیکھ کر یقین آجاتا ہے کہ یہ اس دھرتی کی بجائے برٹش راج کو ہی ایک سیلوٹ ہے اور یہ ناول تعصب اور نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے وہی خدمت انجام دے رہا ہے جو انگریز بہادر نے دی تھی۔ اگر بات انڈیا پاکستان کی تعصب پر مبنی فلموں کی ہو تو دوسرے گروہ کی اتنی تحقیر قبولیت کی سند پاتی ہے لیکن ناول کا فن اس جانبداری کو کبھی بھی قبول نہیں کر پاتا اور بیانیے کو فن کے اعلیٰ مقام سے گرا کر گروہی اور فرقہ وارانہ ادب کی نچلی تہہ تک لے جاتا ہے۔
بیانیے کے اس سارے تجزیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناطق صاحب نے ناول کا بیانیہ تعمیر کرتے وقت پیچھے مُڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ورنہ درج بالابہت سی غلطیاں تو ایک دفعہ کی نظرِ ثانی میں ہی رفع ہو سکتی تھیں۔ لوگوں کے نام بھول جانا، تعداد بھول جانا، وقت اور جگہ کا شعور ختم ہو جانا۔ان کے علاوہ بیانیے کی تعمیر میں کچھ ایسی کج روی ہے کہ مسیحائی کے لیے خضر درکار ہے۔بیانیے میں پورا ڈھانچہ ایک ہی انداز میں تعمیر نہیں ہوتا۔فنکار کو ہر تھوڑی دیر بعد نئے انداز کی تحریر لکھنی پڑتی ہے اور ہر دفعہ اس کا بنیادی مزاج ہی الگ ہو جاتا ہے۔ ناطق صاحب کے اس ناول میں بیانیے کے اندر یہ پانچ انداز موجود ہیں۔ بیانیہ، وضاحتیہ،مکالمہ، رپورٹ ، تقریر۔لیکن فاضل مصنف کو کسی جگہ بھی یہ احساس تک نہیں ہواکہ انھیں انداز بدلنا چاہیے۔ جس زبان میں مکالمے لکھے ہیں، اسی زبان میں رپورٹ بھی درج کر دی ہے۔ جو انداز Narrationکا ہے، وہی Descriptionکے وقت نظر آتا ہے۔ کردار کوئی بھی ہو، ایک ہی جیسا طرزِ تکلم اپنائے رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انگریز، مسلمان اور سکھ بھی ایک ہی طرح کا محاورہ بولتے ہیں۔ناطق صاحب کو زبان کے مختلف انداز اور لہجوں کا شعور تک نہیں ہے اور اپنے ناتواں کندھوں پر ناول جیسی ذمہ داری کا بوجھ لے لیا ہے جو صبرِ صمیم کے ساتھ ساتھ زبان پر استادانہ گرفت کا بھی متقاضی ہے۔پورے بیانیے کا جائزہ لیا جائے تو تحریر جذبے سے بالکل خالی نظر آتی ہے۔ رواروی میں اور تیزی سے لکھی گئی ایک ایسی تحریر ہے جسے نپٹانے ، انجام تک لانے اور چھپوانے تک ہر کام میں مصنف کو جلدی تھی اوراسی جلدی نے انھیں محنت بھی نہیں کرنے دی ۔ناول کا موضوع جو بھی ہو، ناول نگار کے لیے یا توبھرپور تجربہ ضروری ہوتا ہے یا پھر انتہا درجے کا مطالعہ۔ اِس ناول میں ان دونوں چیزوں کی عدم موجودگی نظر آتی ہے۔ تجربہ تو ظاہر ہے ناطق صاحب کو ہو ہی نہیں سکتا تھا، بات ہی اسّی سال پرانی ہے۔ تخیل کا کچا پن واضح نظر آتا ہے لیکن اس کے متوازی مطالعے کا بھی بہت فقدان ہے۔تن آسانی حاوی تھی اور فاضل مصنف نے پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھنے کی بجائے آگے لکھتے چلے جانے کو ترجیح دی۔ نتیجتاً انھوں نے غلطیوں کا یہ شاہکار تخلیق کیا۔ ان سب خامیوں کے باوجود کوئی اگر انھیں ناول نگار مانتا ہے تو پھر اردو ناول اور اردو ناول کے نقادوں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں صرف مثال کے طور پر صلاح الدین درویش اور حیدر سید کے ایک ایک کمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو انھوں نے ناطق صاحب کی ایک پوسٹ پر کیا تھا۔ ادبی طرف داری اور دوست پروری کی عظیم مثالیں ہیں۔ ورنہ ’’کئی چاند تھے سرِ آسماں‘‘ جیسے لسانی اور تہذیبی شاہکار کے ساتھ ’’نولکھی کوٹھی‘‘ جیسی بچگانہ کاوش کا نام لینا ہی گناہ ہے۔
nolakhi kothi is better than…kai chand thy sary asmaan….geo serzameeny okara…..love you natiq.
22.11.2015 کو ناطق صاحب کی پوسٹ پرصلاح الدین درویش کا کمنٹ۔
’’اردو زبان کا سب سے بڑا افسانہ نگار ناول نگار ادیب اور نقاد شمس الرحمن فاروقی نہیں ہے۔ یہ الفاظ علی اکبر ناطق کے لیے ہی زیبا ہیں۔‘‘
01.11.2015 کو ناطق صاحب کی پوسٹ پرحیدر سید کا کمنٹ۔
ناول میں کہانی اور بیانیے کے بعد اہم چیز زبان ہوتی ہے۔کہانی اہم ہے لیکن اس کہانی کی پیش کش کیوں کہ زبان کے ذریعے ہی ہوتی ہے تو یہ زبان بنیادی عنصرہے۔ لفظ ناول کی اکائی ہیں اور ان اکائیوں کا استعمال اگر درست ہو گا تو ناول نگار کا ابلاغ ہو گا۔ اگر زبان فصیح و بلیغ نہ ہو، اپنی خوبصورتی قائم نہ رکھے تو اس بیانیے کا معیار انتہائی پست ہو گا۔ زبان ہی ناول نگار کا میڈیم ہے اور اگر اپنے میڈیم کا شعور ہی نہ ہو تو پھر اس نے لکھنا خاک ہے ۔ موسیقار کو سُروں کی پہچان نہ ہو، مصور کو رنگوں کے استعمال پر عبور نہ ہو تو ان سے فنکاری کی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ ناطق صاحب لکھتے وقت قلم برداشتہ لکھتے ہیں اور اگر بیدی کے لفظ مستعار لیے جائیں تو ’نہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں، نہ لکھتے وقت سوچتے ہیںاورنہ ہی لکھنے کے بعد سوچتے ہیں۔‘ نظرِ ثانی شاید کی ہی نہیں گئی۔ پروف کی بے شمار غلطیوں کے ساتھ ساتھ تمام ناول کے مکالموں میں واوین کا عدم استعمال واضح بتاتا ہے کہ کسی بھی معقول آدمی کو مسودہ دکھانے کی بھی زحمت نہیں کی گئی۔پورے ناول میں مکالمہ اور بیانیہ آپس میں دست و پا ہیں۔ اکثر جگہوں پر یہ سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کہ کہاں مکالمہ ختم ہو گیا اور کس جگہ سے بیانیہ شروع ہو گیا۔آج تک کسی زبان کا کوئی ناول واوین سے مبرا نہیں دیکھا گیا اور ناطق صاحب کو اپنا شاہکار چھپوانے میں اتنی جلدی تھی کہ واوین ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ خیر یہ تو پروف کی غلطی ہے، ناطق صاحب نے زبان کی اتنی غلطیاں کی ہیں کہ مجھ جیسے غیر اہلِ زبان کے لیے بھی گننا دشوار ہو گیا تھا ۔ کوئی اہلِ زبان ہوتا تو شاید ان جملوں کو نشان زد کرنے میں سہولت محسوس کرتا جہاں زبان مناسب برتی گئی ہے۔ خیر فہرست سازی کی بجائے چند اقسام کی غلطیوں کی نشاندہی کیے دیتا ہوں۔
زبان کو برتنے میں علی اکبر ناطق صاحب بہت واضح قسم کی غلطیاں کر جاتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسی کہ بیانیے کے اندرسخت ناگوار گزرتی ہیں۔ درج ذیل جملے ملاحظہ کیجیے اور ناطق صاحب کی لسانی مہارت کی داد دیجیے:
۱۔ ولیم نے چاروں طرف غائر نظر ماری۔ ص:25۔(غائر نظر غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں اور نظر مارنا سرسری دیکھنے کو کہتے ہیں۔ یوں ’غائرنظر ماری ‘شترگربہ بنا ہوا ہے۔)
۲۔ ولیم کو سرسری نظر میں ان کی باہر نکلی ہوئی توندیں اور بغیر بالوں کی چندھیائیں دِکھنے سے باز نہ رہ سکیں۔ ص:27(اللہ بخشے۔ چھٹی جماعت میں انگلش کے استاد کے پڑھائے گئےPassive voiceکے جملے یاد آگئے۔ وہ اردو میں اسی طرح لکھواتے تھے۔ مالی کی طرف سے پودوں کو پانی دیا گیا۔ جاوید میاں داد کی طرف سے ایک شاندار سنچری بنائی گئی۔)
۳۔ ہیلے نے کچھ دیر ولیم کی نیلی آنکھوں میں ، جن میں ہلکا سبز رنگ بھی گھلا تھا، دیکھتے ہوئے ایک بھرپور خاموشی کا سوال کیا۔ ص:29۔(’بھرپور خاموشی کا سوال‘ قابلِ دا د ہے۔)
۴۔ وہ کچھ دیر ضرور باہر کی ہوا دیکھتا مگر سفر کی تھکاوٹ نے اسے اس بات پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ ص:25۔ (ہوا دیکھنے کا محاورہ کمال ہے)
۵۔ باقی تمام اضلاع میں اتنی نفری کسی بھی علاقے سے نہیں مل سکی تھی۔ ص:330(کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی نفری کسی اور ضلعے سے نہیں مل سکی تھی۔)
۶۔ یہ شان و شوکت تو واقعی غلام حیدر کی ذات کو نوابوں سے کم نہیں دکھاتی تھی اور ان سب سے بڑھ کر وہ رائفل جو اپنے کارنامے بھری دنیا کی انگریزی سرکار میں دکھا چکی تھی۔ ص:343
۷۔بیر سنگھ بولا:’’ سودھا سنگھ کو اس کی حویلی میں گرفتار کر کے لائوں گا۔‘‘ ص:114(حالانکہ کہنا یہ ہے کہ حویلی میں سے گرفتار کر کے لائوں گا۔)
۸۔ حویلی کے دروازے کی بلیّوں کے حوالے سے انھوں نے دو جگہ پر بالکل متضاد محاورہ استعمال کیا ہے۔ پہلے لکھا تھا :
’’حویلی کے سب دروازوں کی بلیّاں چڑھا دی گئیں۔ ‘‘ ص:20
پھر دو ہی صفحوں کے بعد ان بلیّوں کے متعلق محاورہ یوں بدل گیا۔
’’پیت سنگھ نے اٹھ کر پھر دروازے کی بلّی گرا دی ‘‘۔ ص:23
دروازہ بند کرنا ہو تو یابّلی چڑھانے کا محاورہ استعمال ہو یابّلی گرانے کا محاورہ استعمال ہو۔ایک دوسرے کے متضاد محاورے استعمال کر کے زبان کا ستیا ناس کر دیاگیا۔
۹۔ غلام حیدر نے جہاں بندوق حاصل کی، وہاں سب لوگ پڑھے لکھے تھے۔ وہاں جب بندوق کا ذکر آیا تو اس کے لیے بندوق کا لفظ استعمال ہوا۔ ص:34۔ جب کہ گائوں میں جب گائوں کے ان پڑھ دیہاتی اس بندوق کو دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے نقطۂ نظر سے بتاتے ہوئے ہر دفعہ رائفل کا لفظ استعمال ہوا۔ ص:52
۱۰۔ سب سے مزے کے جملے تو وہ ہیں جہاں حرفِ ندائیہ پنجابیوں کی بجائے اہلِ زبان کا سا ہے۔۔ ایک جگہ شریفاں اپنے بیٹے فضل دین کو یوں جھڑکتی ہے۔’’کیوں بے۔ اتنی دیر کیوں لگا دیتا ہے۔ ‘‘ ص: 16۔دوسری جگہ ملک رفیق پائولی یوں کہتا ہے:’’ اچھا میاں بہزاد،میں بھی چلتا ہوں۔‘‘ص:194۔( یوں لگتا ہے جیسے فیروز پور کے دیہی علاقے کی بجائے دہلی کی گلی قاسم جان میں پہنچ گئے ہوں۔ )